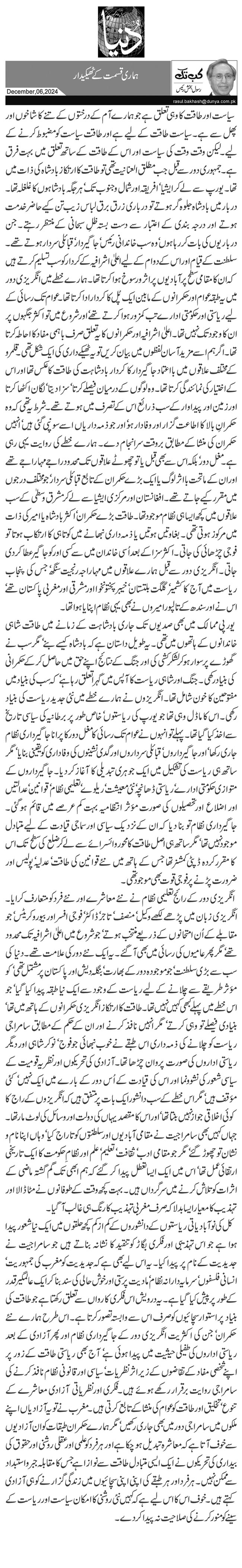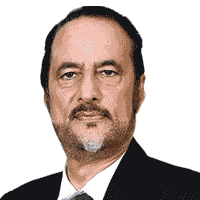ہماری قسمت کے ٹھیکیدار
سیاست اور طاقت کا وہی تعلق ہے جو ہمارے آم کے درختوں کے تنے کا شاخوں اور پھل سے ہے۔ سیاست طاقت کے لیے ہے اور طاقت سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے۔ لیکن وقت وقت کی سیاست اور اس کے طاقت کے ساتھ تعلق میں بہت فرق ہے۔ جمہوری دور سے قبل جب مطلق العنانیت تھی تو طاقت کا ارتکاز بادشاہ کی ذات میں تھا۔ یورپ سے لے کر ایشیا‘ افریقہ اور شمال وجنوب تک‘ ہر جگہ بادشاہوں کا غلغلہ تھا۔ دربار میں بادشاہ جلوہ گر ہوتے تو درباری زرق برق لباس زیب تن کیے حاضر خدمت ہوتے اور درجہ بندی کے اعتبار سے دست بستہ ظلِ سبحانی کے منتظر رہتے۔ جن درباریوں کی بات کر رہا ہوں‘ وہ سب خاندانی رئیس‘ جاگیردار‘ قبائلی سردار ہوتے تھے۔ سلطنت کے قیام اور اس کے دوام کے لیے اعلیٰ اشرافیہ کے کردار کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا مقامی سطح پر آبادیوں پر اثر ورسوخ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے خطے میں انگریزی دور میں یہ طبقہ عوام اور حکمرانوں کے مابین ایک پُل کا کردار ادا کرتا تھا۔ عوام تک رسائی کے لیے ریاستی اور حکومتی ادارے تب کمزور ہوا کرتے تھے‘ اور شروع میں تو اکثر جگہوں پر ان کا وجود تک نہیں تھا۔ اعلیٰ اشرافیہ اور حکمرانوں کا یہ تعلق صرف باہمی مفاد کا احاطہ کرتا تھا۔ اگر ہم اسے مزید آسان لفظوں میں بیان کریں تو یہ ٹھیکے داری کی ایک شکل تھی۔ قلمرو کے مختلف علاقوں میں بااعتماد جاگیردار کا کردار بادشاہت کی طاقت کا عکس تھا اور اس کے اختیار کی نمائندگی کرتا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا‘ سزا دیتا‘ لگان اکٹھا کرتا اور زمین اور پیداوار کے سب ذرائع اس کے تصرف میں ہوتے تھے۔ شرط یہ تھی کہ وہ حکمرانِ بالا کا اطاعت گزار اور وفادار ہو‘ اور جو ذمہ داریاں اسے سونپی گئی ہیں‘ انہیں حکمران کی منشا کے مطابق بروقت سرانجام دے۔ ہمارے خطے کی روایت یہی رہی ہے۔ مغل دور‘ بلکہ اس سے بھی قبل یا تو چھوٹے علاقوں تک محدود راجے مہاراجے تھے اور ان کے ماتحت بااثر لوگ یا ایک بڑے حکمران کے تابع قبائلی سردار‘ جو مختلف درجوں میں مقرر کیے جاتے تھے۔ افغانستان اور مرکزی ایشیا سے لے کر مشرق وسطیٰ کے سب علاقوں میں کچھ ایسا ہی نظام موجود تھا۔ طاقت بڑے حکمران‘ اکثر بادشاہ یا امیرکی ذات میں مرکوز ہوتی تھی۔ بغاوتیں ہوتیں یا ذمہ داری نبھانے میں کوتاہی کا ارتکاب ہوتا تو فوجی چڑھائی کی جاتی۔ اکثر سزا کے بعد اُسی خاندان میں سے کسی اور کو جاگیر عطا کر دی جاتی۔ انگریزی دور سے قبل ہمارے علاقوں میں مہاراجہ رنجیت سنگھ‘ جس کی پنجاب ریاست میں آج کا کشمیر‘ گلگت بلتستان‘ خیبر پختونخوا اور مشرقی اور مغربی پاکستان تھے‘ اس نے اور سندھ کے تالپور امیروں نے بھی یہی نظام اپنایا ہوا تھا۔
یورپی ممالک میں بھی صدیوں تک جاری بادشاہت کے زمانے میں طاقت شاہی خاندانوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ طویل داستان ہے کہ بادشاہ کیسے بنے‘ مگر سب نے گھوڑے پر سوار ہوکر لشکر کشی کی اور جنگ کے نتائج اپنے حق میں حاصل کر کے حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ جنگ اور شاہی ریاست کا آپس میں گہرا تعلق رہا ہے‘ کہ سب کی بنیاد میں مفتوحین کا خون شامل تھا۔ انگریزوں نے ہمارے خطے میں نئی جدید ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس کا ماڈل وہی تھا جو یورپ کی ریاستوں‘ خاص طور پر برطانیہ کی سیاسی تاریخ سے اخذ کیا گیا تھا۔ پہلے تو انہوں نے عوام تک رسائی کا مغل دور کا پرانا جاگیرداری نظام جاری رکھا‘ اور جاگیرداروں‘ قبائلی سرداروں اور گدی نشینوں کی وفاداری کو یقینی بنایا‘ مگر ساتھ ہی ریاست کی تشکیل میں ایک جوہری تبدیلی کا آغاز کر دیا۔ جاگیرداروں کے متوازی حکومتی ادارے‘ ریاستی ڈھانچہ‘ نئی معیشت‘ ریلوے‘ تعلیمی نظام‘ قوانین‘ عدالتیں اور اضلاع اور تحصیلوں کی صورت مؤثر انتظامیہ بہت کم عرصے میں قائم ہو گئی۔ جاگیرداری نظام تو بنا دیا کہ ان کے نزدیک سیاسی اور سماجی قیادت کے لیے متبادل موجود نہیں تھا‘ مگر ساتھ ہی اصل طاقت کا محور وائسرائے سے لے کر ضلع کی سطح تک اس کا مقرر کردہ ڈپٹی کمشنر تھا جس کے ہاتھ میں نئے قوانین کی طاقت‘ عدلیہ‘ پولیس اور ضرورت پڑنے پر فوجی قوت بھی موجود تھی۔
انگریزی دور کے رائج تعلیمی نظام نے نئے معاشرے اور نئے فرد کو متعارف کرایا۔ انگریزی زبان میں پڑھے لکھے وکیل‘ منصف‘ تاجر‘ ڈاکٹر‘ فوجی افسر اور بیورو کریٹس‘ جو مقابلے کے اُن امتحانوں کے ذریعے منتخب ہوتے‘ جو شروع میں اعلیٰ اشرافیہ تک محدود تھے‘ مگر پھر عامیوں کی رسائی میں بھی آ گئے۔ یہ ایک نئے دور کی علامت تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت‘ جو موجودہ دور کے بھارت‘ بنگلہ دیش اور پاکستان پر مشتمل تھی‘ کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے ریاست کے وجود سے ایک نیا طبقہ پیدا کیا گیا‘ جو اس خطے میں پہلے کبھی کہیں نہیں تھا۔ طاقت کا ارتکاز انگریزی حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا‘ بنیادی فیصلے تو وہی کرتے‘ مگر انہیں نافذ کرنے اور ان کے حکم کے مطابق سامراجی ریاست کو چلانے کی ذمہ داری اس طبقے نے خوب نبھائی جو فوج‘ نوکر شاہی اور دیگر ریاستی اداروں کی صورت پروان چڑھا تھا۔ آزادی کی تحریکوں اور نظریہ قومیت کے سیاسی شعور کی نشوونما اور اس کی قیادت کے اُس دور کے بارے میں ایک نہیں‘ کئی مؤقف ہیں‘ مگر اس خطے کے سب دانشور ایک بات پر متفق ہیں کہ انگریزوں کے راج کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا تھا‘ اور اس کا مقصد یہاں کی دولت اور وسائل کی لوٹ مار تھا۔ جہاں کہیں بھی سامراجیت نے مقامی آبادیوں اور سلطنتوں کو تاراج کیا‘ وہاں اپنا نام و نشان تو چھوڑ گئے‘ مگر جو مقامی ادب‘ ثقافت‘ تعلیم‘ علم اور نظامِ حکومت کا ایک تاریخی ارتقائی عمل تھا‘ اس میں ایک ایسا تعطل پیدا کر گئے کہ ہم ابھی تک گم گشتہ ماضی کے اثرات کو تلاش کرنے میں سرگرداں ہیں۔ بہت کچھ وقت کے طوفانوں نے مٹا ڈالا اور تہذیب کا معیار ایسا بدلا کہ صرف مغربی تہذیب کا رنگ ہی غالب آ گیا۔
کل کی نوآبادیاتی ریاستوں کے دانشوروں کے کم از کم کچھ حلقوں میں ایک نیا شعور پیدا ہوا ہے جو اس تہذیبی اور فکری بگاڑ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو سامراجیت نے جدیدیت کے نام پر پیدا کیا۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ جدیدیت کو مغرب کی جمہوریت‘ انسانی فلسفوں‘ سرمایہ دارانہ نظام‘ مادیت پرستی اور خوش حالی کی سند بنا کر ایک عالمگیر قدر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ درویش اس فکری کارواں سے تعلق رکھتا ہے جو طاقت کی بنیاد پر استوار سچائیوں کو صرف اس سے وابستہ تصور کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے نئے حکمران‘ جن کی اکثریت انگریزی دور کے جاگیرداری نظام اور پھر آزادی کے بعد ریاستی اداروں کی طفیلی حیثیت میں پیدا ہوئی ہے‘ آج بھی ریاستی طاقت کے زور پر اپنے شخصی مفاد کے تقاضوں کے زیر اثر نظریات‘ سیاسی اور قانونی نظام نافذ کرنے کی سامراجی روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ فکری اور نظریاتی آزادی معاشرے کے تنوع‘ تخلیق اور طاقت کو عوام کی منشا کے تابع کرتی ہیں۔ مغرب نے تو یہ آزادیاں اپنے ملکوں میں سامراجی دور میں بھی جاری رکھیں‘ مگر ہمارے حکمران طبقات کو ان آزادیوں سے خوف آتا ہے کہ معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے ا ور ہر فرد کو علمی اور عقلی روشنی اور حقوق کی بیداری کی تحریکوں نے ایک ایسی متبادل طاقت سے نوازا ہے جس کا مقابلہ جبر واستبداد سے ممکن نہیں۔ ہر فرد اور ہر طبقے کی اپنی اپنی سچائیوں میں زندگی گزارنے کو ہی آزادی کہتے ہیں۔ خوف اس کا اس لیے ہے کہ کہیں نئی روشنی کا امکان سیاست اور ریاست کے سینے کو منور کرنے کی صلاحیت نہ پیدا کر دے۔