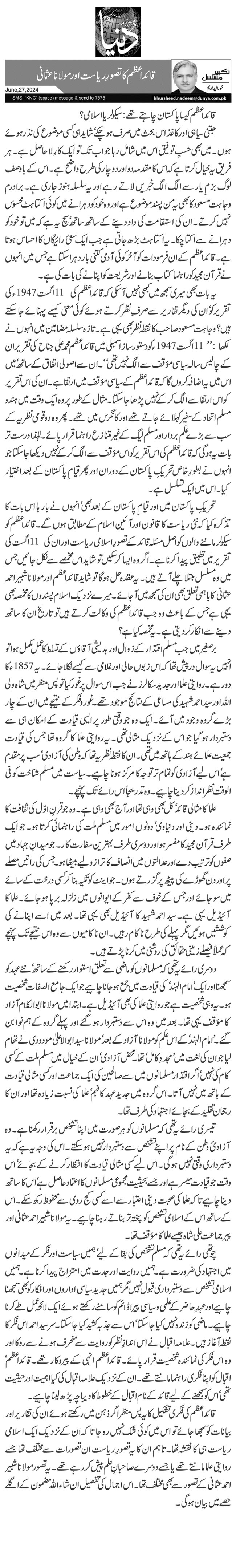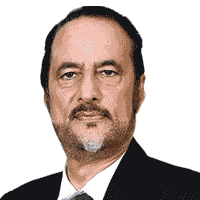قائداعظم کا تصورِ ریاست اور مولانا عثمانی
قائداعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے: سیکولر یا اسلامی؟
جتنی سیاہی اور کاغذ اس بحث میں صرف ہو چکے‘ شاید ہی کسی موضوع کی نذر ہوئے ہوں۔ میں بھی حسبِ توفیق اس میں شامل رہا جو اب تک تو ایک کارِ لاحاصل ہے۔ ہر فریق یہ خیال کر تا ہے کہ اس کا مقدمہ دو اور دو چار کی طرح واضح ہے۔ اس کے باوصف لوگ بزمِ یار سے الگ الگ خبریں لاتے رہے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ برادرم وجاہت مسعود کا بھی یہ من پسند موضوع ہے اور وہ خود کو دہرانے میں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ ان کی استقامت کی داد دینے کے ساتھ ساتھ‘سچ یہ ہے کہ میں تو خود کو دہرانے سے اکتا چکا۔ یہ اکتاہٹ بڑھ جاتی ہے جب ایک سعیٔ رائیگاں کا احساس ہوتا ہے۔ قائداعظم کے ان فرمودات کو آخر کوئی آدمی کتنی بار دہرا سکتا ہے جس میں انہوں نے قرآن مجید کو راہنما کتاب بنانے اور شریعت کو اپنانے کی بات کی ہے۔
یہ بات بھی میری سمجھ میں کبھی نہیں آ سکی کہ قائداعظم کی 11 اگست 1947ء کی تقریر کو‘ ان کی دیگر تقاریر سے صرفِ نظر کرتے ہوئے کوئی معنی کیسے پہنائے جا سکتے ہیں؟ وجاہت مسعود صاحب کا نقطہ نظر بھی یہی ہے۔ تازہ سلسلہ مضامین میں انہوں نے لکھا: ''11 اگست 1947ء کو دستور ساز اسمبلی میں قائداعظم محمد علی جناح کی تقریر ان کے چالیس سالہ سیاسی مؤقف سے الگ نہیں تھی‘‘۔ ان سے اصولی اتفاق کے ساتھ‘ میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ قائداعظم کے سیاسی مؤقف میں ارتقا ہے۔ ان کی اس تقریر کو اس ارتقا سے الگ کر کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ مثال کے طور پر وہ ایک وقت میں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے جاتے تھے اور کانگرس میں تھے۔ پھر وہ دو قومی نظریہ کے سب سے بڑے عَلم بردار اور مسلم لیگ کے غیر متنازع راہنما قرار پائے۔ لہٰذا درست تر بات یہ ہو گی کہ قائداعظم کی اس تقریر کو اس مؤقف سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا جو انہوں نے بطورِ خاص تحریکِ پاکستان کے دوران اور پھر قیامِ پاکستان کے بعد اختیار کیا۔ اس میں ایک تسلسل ہے۔
تحریکِ پاکستان میں اور قیامِ پاکستان کے بعد بھی‘ انہوں نے بار ہا اس بات کا تذکرہ کیا کہ نئی ریاست کا قانون اور آئین اسلام کے مطابق ہوں گے۔ قائداعظم کو سیکولر ماننے والوں کو اصل مسئلہ قائد کے تصورِ اسلامی ریاست اور ان کی 11 اگست کی تقریر میں تطبیق پیدا کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا کر سکیں تو شاید اس مخمصے سے نکل جائیں جس میں وہ مسلسل مبتلا چلے آتے ہیں۔ یہ عقدہ حل ہو گا تو شاید قائداعظم اور مولانا شبیر احمد عثمانی کا باہمی تعلق بھی ان کی سمجھ میں آ جائے۔ میرے نزدیک اسلام پسندوں کا مخمصہ بھی یہی ہے جس کے باعث وہ جب قائداعظم کی وکالت کرتے ہیں تو تاریخ ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ مخمصہ کیا ہے؟
برصغیرمیں جب مسلم اقتدار کے زوال اور بدیشی آقاؤں کے تسلط کا عمل مکمل ہوا تو انہیں یہ سوال درپیش تھا کہ اس زبوں حالی اور غلامی سے کیسے نکلا جائے۔ یہ 1857ء کا دور ہے۔ روایتی علما اور جدید سکالرز نے جب اس سوال پر غور کیا تو پس منظر میں شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید کی مساعی کے نتائج موجود تھے۔ غور وفکر کے نتیجے میں ان کے چار بڑے گروہ وجود میں آئے۔ ایک وہ جو وقتی طور پر ایسی قیادت کے امکان ہی سے دستبردار ہو گیا جو اس کے نزدیک مثالی تھی۔ یہ روایتی علما کا گروہ تھا جس کی قیادت جمعیت علمائے ہند کے ہاتھ میں تھی۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وطن کی آزادی‘ سب پر مقدم ہے‘ اس لیے آزادی کو تمام تر توجہ کا مرکز ہونا چاہیے۔ سیاست میں مسلم شناخت کو فی الوقت نظر انداز کر دینا چاہیے۔ وہ تدریجاً اس رائے تک پہنچے۔
علما کا مثالی قائد‘ کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے۔ وہ جو قرنِ اوّل کی ثقافت کا نمائندہ ہو۔ دینی اور دنیاوی‘ دونوں امور میں مسلم ملت کی راہنمائی کرتا ہو۔ جو ایک طرف قرآن مجید کا مفسر ہو اور دوسری طرف بہترین سفارت کار۔ جو میدانِ جہاد میں صفوں کو ترتیب دے اور عدالتوں میں انصاف کا ترازو لیے بیٹھا ہو۔ جس کی راتیں مصلے پر اور دن گھوڑے کی پیٹھ پر گزرتے ہوں۔ جو اینٹ کو تکیہ بنا کر کسی درخت کے سائے میں سو جائے اور جس کے خوف سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جائے۔ علماکا آئیڈیل یہی ہے۔ سید احمد شہید کا آئیڈیل بھی یہی تھا۔ بعد میں اسے اپنانے کی کوششیں ہوئیں مگر پہلے کی طرح ناکام رہیں۔ ان ناکامیوں سے وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ عملاً فیصلے زمینی حقائق کی روشنی میں کرنا پڑتے ہیں۔
دوسری رائے یہ تھی کہ مسلمانوں کو ماضی سے تعلق استوار رکھنے کے ساتھ‘ نئے عہد کو سمجھنا اور ایک 'امام الہند‘ کی قیادت میں جمع ہو جانا چاہیے جو ایک جامع الصفات شخصیت ہو۔ یہ وہی شخصیت ہے جو روایتی علما کی بھی آئیڈیل ہے۔ ابتدا میں مولانا ابوالکلام آزاد کا مؤقف یہی تھا۔ بعد میں وہ اس سے دستبردار ہو گئے اور پہلے گروہ کے ہم نوا بن گئے۔ 'امام الہند‘ کے اس عَلم کو مولانا آزاد کے بعد‘ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے تھام لیا جو ان کی لغت میں 'مجددِ کامل‘ تھا۔ محض آزادی‘ ان کے خیال میں مسلم ملت کے کسی کام کی نہیں‘ اگر اقتدار مسلمانوں میں سے صالحین کی ایک جماعت اور کسی مثالی قیادت کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اس گروہ میں جدید عہد کا فہم‘ علما کی نسبت زیادہ تھا اور ان کا رجحان تقلید کے بجائے اجتہاد کی طرف تھا۔
تیسری رائے یہ تھی کہ مسلمانوں کو ہر صورت میں اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے۔ وہ آزادیٔ وطن کے نام پر اپنے تشخص سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دستبرداری وقتی نہیں ہو گی۔ اس لیے کسی مثالی قیادت کا انتظار کرنے کے بجائے‘ اس وقت جو قیادت میسر ہے اور جسے بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہے‘ اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ علما کی صحبت دینی اعتبار سے اسے کسی کج روی سے محفوظ رکھ سکے۔ اس کے ساتھ اس کے اسلامی تشخص کو پختہ تر بناتے رہنا چاہیے۔ یہ مولانا شبیر احمد عثمانی اور پیر جماعت علی شاہ جیسے علما کا مؤقف تھا۔
چوتھی رائے یہ تھی کہ مسلم تشخص کی بقا کے لیے‘ ہمیں سیاست اور فکر کے میدانوں میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ ہمیں روایت اور جدت میں امتزاج پیدا کرنا ہے۔ ہمیں اسلامی تشخص سے دستبرداری قبول نہیں مگر ہمیں جدید سیاسی اداروں اور افکار کو بھی سمجھنا چاہیے اور عہدِ حاضر کے علمی و سیاسی پیراڈائم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ ماضی کو زندہ نہیں کیا جا سکتا‘ اس سے جذبہ کشید کیا جا سکتا۔ سر سید احمد اس فکر کا نقطہ آغاز ہیں۔ علامہ اقبال نے اس اندازِ نظر کو روایت سے منحرف ہونے سے روکا اور وہ اس فکر کی نمائندہ شخصیت قرار پائے۔ قائداعظم انہی کے پیروکار تھے۔ قائداعظم‘ اقبال کو اپنا فکری راہنما مانتے تھے۔ ان کے نزدیک علامہ اقبال کی کیا اہمیت اور حیثیت تھی‘ اس کو سمجھنے کے لیے قائد کے نام اقبال کے خطوط کا دیباچہ پڑھ لینا چاہیے۔
قائداعظم کی فکری تشکیل کا یہ پس منظر اگر ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی تقاریر اور بیانات کو سمجھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ ان کے نزدیک ایک اسلامی ریاست ہی کا نقشہ تھا۔ تاہم ان کا یہ تصورِ ریاست ان تصورات سے مختلف تھا جسے روایتی علما مانتے تھے یا جسے دوسرے صاحبانِ علم پیش کر رہے تھے۔ یہ تصور مولانا شبیر احمد عثمانی کے تصور سے بھی مختلف تھا۔ اس اجمال کی تفصیل ان شاء اللہ مضمون کے اگلے حصے میں بیان ہو گی۔