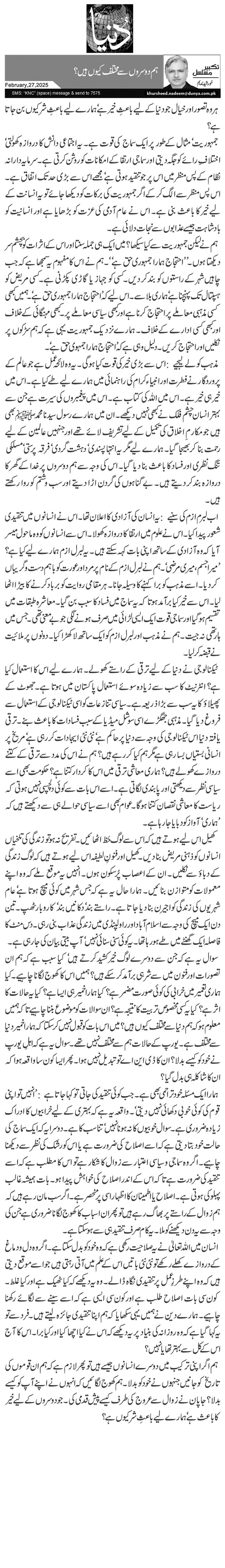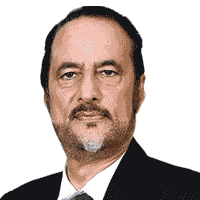ہم دوسروں سے مختلف کیوں ہیں؟
ہر وہ تصور اور خیال جو دنیا کے لیے باعثِ خیر ہے‘ ہمارے لیے باعثِ شر کیوں بن جاتا ہے؟
جمہوریت‘ مثال کے طور پر ایک سماج کی قوت ہے۔ یہ اجتماعی دانش کا دروازہ کھولتی‘ اختلافِ رائے کو جگہ دیتی اور سماجی ارتقا کے امکانات کو روشن کرتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے پس منظر میں اس پر جو تنقید ہوتی ہے‘ مجھے اس سے بڑی حد تک اتفاق ہے۔ اس پس منظر سے الگ کر کے اگر جمہوریت کی برکات کو دیکھا جائے تو یہ انسانت کے لیے خیر کا باعث بنی ہے۔ اس نے عام آدمی کی عزت کو بڑھایا ہے اور انسانیت کو بادشاہت جیسے عذابوں سے نجات دلائی ہے۔
ہم نے لیکن جمہوریت سے کیا سیکھا؟ میں ایک ہی جملہ سنتا اور اس کے اثرات کو بچشم سر دیکھتا ہوں۔ ''احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے‘‘۔ ہم نے اس کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ جب چاہیں شہر کے راستوں کو بند کر دیں۔ کسی کو جہاز یا گاڑی پکڑنی ہے۔ کسی مریض کو ہسپتال تک پہنچنا ہے‘ ہماری بلا سے۔ اس لیے کہ 'احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے‘۔ ہمیں کبھی کسی مذہبی معاملے پر احتجاج کرنا ہے اورکبھی سیاسی معاملے پر۔ کبھی مہنگائی کے خلاف اور کبھی کسی ادارے کے خلاف۔ ہمارے نزدیک جمہوریت یہی ہے کہ ہم سڑکوں پر نکلیں اور احتجاج کریں۔ دلیل وہی ہے کہ 'احتجاج ہمارا جمہوی حق ہے‘۔
مذہب کو لے لیجیے: اس سے بڑی خیر کی قوت کیا ہو گی۔ یہ وہ لائحہ عمل ہے جو عالم کے پروردگار نے فطرت اور انبیاء کرام کی راہنمائی میں ہمارے لیے طے کیا ہے۔ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس میں اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں پیغمبروں کی سیرت ہے جن سے بہتر انسان چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھے۔ ان میں ہمارے رسول سیدنا محمدﷺ بھی ہیں جو مکارمِ اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے تھے اور جنہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہمارے لیے مگر یہ انتہا پسندی‘ دہشت گردی‘ فرقہ پرستی‘ مسلکی تنگ نظری اور فساد کا باعث بنا دیا گیا۔ اس کی وجہ سے ہم دوسروں پر خدا کے گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ بے گناہوں کی گردن اڑا دیتے اور سب و شتم کو روا رکھتے ہیں۔
اب لبرم ازم کی سنیے: یہ انسان کی آزادی کا اعلان تھا۔ اس نے انسانوں میں تنقیدی شعور پیدا کیا۔ اس نے علوم میں ارتقا کا دروازہ کھولا۔ اس سے انسانوں کو وہ ماحول میسر آیا کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ لبرل ازم ہمارے لیے کیا ہے؟ 'میرا جسم، میری مرضی‘۔ ہم نے لبرل ازم کے نام پر مرد اور عورت کو باہم دست و گریباں کر دیا۔ اسے مذہب کو برا کہنے کا وسیلہ جانا۔ ہر مقامی روایت کو برباد کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اس سے خیر کیا برآمد ہوتا کہ یہ سماج میں فساد کا سبب بن گیا۔ معاشرہ طبقات میں تقسیم ہو گیا اور سماجی قوت ایک ایسی لڑائی میں صرف ہونے لگی جو بے معنی تھی۔ جس میں ہار تھی نہ جیت۔ ہم نے مذہب اور لبرل ازم کو ایک ساتھ لا کھڑا کیا۔ دونوں پر ملائیت نے قبضہ کر لیا۔
ٹیکنالوجی نے دنیا کے لیے ترقی کے راستے کھولے۔ ہمارے لیے اس کا استعمال کیا ہے؟ انٹرنیٹ کا سب سے زیادہ سوئے استعمال پاکستان میں ہوتا ہے۔ جھوٹ کے پھیلاؤ کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سیاسی تنازعات کو اسی ٹیکنالوجی کے استعمال سے فروغ دیا گیا۔ مذہبی جھگڑے اسی سوشل میڈیا کے سبب فسادات کا باعث بنے۔ ترقی یافتہ دنیا اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا پر حاکم ہے‘ نئی نئی ایجادات کر رہی ہے‘ مریخ پر انسانی بستیاں بسا رہی ہے مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کی مدد سے ترقی کے کتنے دروازے کھولے ہیں؟ ہماری معاشی ترقی میں اس کا کردار کتنا ہے؟ حکومت بھی اسے سیاسی نظر سے دیکھتی اور پابندی لگاتی ہے۔ اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ ریاست کا معاشی نقصان کتنا ہو گا۔ عوام بھی اسے سیاسی حوالے ہی سے دیکھتے ہیں کہ 'ہماری‘ آواز کو دبایا جا رہا ہے۔
کھیل اس لیے ہوتے ہیں کہ اس سے لوگ حَظ اٹھائیں۔ تفریح نہ ہو تو زندگی کی تلخیاں انسانوں کو ذہنی مریض بنا دیں۔ کھیل اور فنونِ لطیفہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ زندگی کے دباؤ سے نکلیں۔ ان کے اعصاب پُرسکون ہوں۔ انہیں یہ موقع ملے کہ وہ اپنے معمولات کو متوازن بنائیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جس شہر میں کوئی میچ ہوتا ہے‘ عام شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جا تا ہے۔ راستے بند‘ دکانیں بند‘ کاروبار ٹھپ۔ تین دن ایک میچ کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں زندگی عذاب بنی رہی۔ دس منٹ کا فاصلہ ایک گھنٹے میں طے ہو رہا تھا۔ یہ کوئی سنی سنائی نہیں‘ آپ بیتی بیان کی جا رہی ہے۔
سوال یہ ہے کہ جن سے دوسرے لوگ خیر کشید کرتے ہیں‘ کیا سبب ہے کہ ہم ان تصورات اور فنون میں سے شر ہی برآمد کر سکے ہیں؟ ہمیں اس کا کھوج لگانا چاہیے۔ کیا ہماری تعمیر میں خرابی کی کوئی صورت مضمر ہے؟ کیا ہمارا خمیر ہی ایسا ہے؟ کیا یہ حالات کا اثر ہے؟ کیا یہ کسی مخصوص تربیت کا نتیجہ ہے؟ ان سوالات کو موضوع بننا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم دنیا سے مختلف کیوں ہیں؟ میں اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ ہمارا خمیر دنیا سے مختلف ہے۔ یورپ کے حالات ہم سے مختلف نہیں تھے۔ سوال یہ ہے کہ اہلِ یورپ نے خود کو کیسے بدلا؟ ان کا ڈی این اے تو تبدیل نہیں ہوا۔ پھر ایسا کون سا واقعہ ہوا کہ ان کا شاکلہ ہی بدل گیا؟
ہمارا ایک مسئلہ خود تراحمی بھی ہے۔ جب کوئی تنقید کی جاتی تو کہا جاتا ہے : 'انہیں تو اپنی قوم کی کوئی خوبی دکھائی نہیں دیتی‘۔ واقعہ یہ ہے کہ بہتری کے لیے خرابیوں کا ادراک زیادہ ضروری ہے۔ سوال خوبیوں کا نہ ہونا نہیں‘ تناسب کا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک سماج کی حالت خود بتا دیتی ہے کہ اسے اصلاح کی ضرورت ہے یا اس کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ سماجی و سیاسی اعتبار سے زوال کا شکار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے تنقید کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اندر اصلاح کی خواہش پیدا ہو۔ بات ہمیشہ غالب پہلو کی ہوتی ہے۔ اصلاح یا اطمینان کا اظہار اسی پر منحصر ہے۔ اگر سب مان رہے ہیں کہ ہم زوال کے راستے پر بھاگ رہے ہیں تو پھر ان اسباب کا کھوج لگانا ضروری ہے جن کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو ملا۔ یہ کام صرف تنقید ہی سے ہو سکتا ہے۔
انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خود کو بدل سکتا ہے۔ اگر وہ دل و دماغ کے دروازے کھلے رکھے تو نئی نئی باتیں اس کے علم میں آتی رہتی ہیں جو اسے موقع دیتی ہیں کہ وہ اپنے طرزِ عمل پر تنقیدی نگاہ ڈالے۔ وہ یہ دیکھے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ کون سی بات اصلاح طلب ہے اور کون سی ایسی ہے کہ اسے سینے سے لگائے رکھنا چاہیے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہم اپنا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ فرد سے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ دیکھے کہ اس نے کیا اچھا کیا اور کیا برا۔ اس کا آج اس کے کل سے بہتر تھا یا نہیں؟
ہم اگر اپنی ترکیب میں دوسرے انسانوں جیسے ہیں تو پھر لازم ہے کہ ہم ان قوموں کی تاریخ کو جانیں جنہوں نے خود کو بدلا۔ ہم کھوج لگائیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بدلا؟ جاپان نے زوال سے عروج کی طرف کیسے پیش قدمی کی۔ جو دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہے‘ ہمارے لیے باعثِ شر کیوں ہے؟