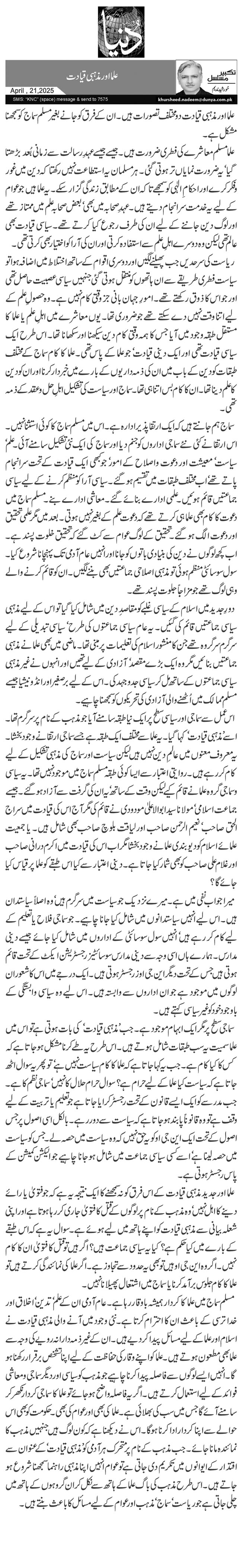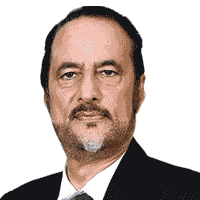علما اور مذہبی قیادت
علما اور مذہبی قیادت دو مختلف تصورات ہیں۔ ان کے فرق کو جانے بغیر مسلم سماج کو سمجھنا مشکل ہے۔
علما مسلم معاشرے کی فطری ضرورت ہیں۔ جیسے جیسے عہدِ رسالت سے زمانی بُعد بڑھتا گیا‘ یہ ضرورت نمایاں تر ہوتی گئی۔ ہر مسلمان یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ دین میں غور وفکر کرے اور احکامِ الٰہی کو سمجھے تاکہ ان کے مطابق زندگی گزار سکے۔ یہ علما ہیں جو عوام کے لیے یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ عہدِ صحابہ میں بھی‘ بعض صحابہ علم میں ممتاز تھے اور لوگ دین جاننے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ سیاسی قیادت بھی عالم تھی لیکن وہ دوسرے اہلِ علم سے استفادہ کرتی اور ان کی آرا کو اختیار بھی کرتی تھی۔
ریاست کی سرحدیں جب پھیلنے لگیں اور دوسری اقوام کے ساتھ اختلاط میں اضافہ ہوا تو سیاست فطری طریقے سے ان ہاتھوں کو منتقل ہوتی گئی جنہیں سیاسی عصبیت حاصل تھی اور جو اس کا ذوق رکھتے تھے۔ امورِ جہان بانی جز وقتی کام نہیں ہے۔ وہ حصولِ علم کے لیے اتنا وقت نہیں دے سکتے تھے جو ضروری تھا۔ یوں معاشرے میں اہلِ علم یا علما کا مستقل طبقہ وجود میں آیا جس کا ہمہ وقتی کام دین سیکھنا اور سکھانا تھا۔ اس طرح ایک سیاسی قیادت تھی اور ایک دینی قیادت‘ جو علما کے پاس تھی۔ علما کا کام سماج کے مختلف طبقات کو دین کے باب میں ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں خبردار کرنا اور ان کو دین کا علم دینا تھا۔ ان کا کام بس اتنا ہی تھا۔ سماج اور سیاست کی تشکیل اہلِ حل وعقد کے ذمہ تھی۔
سماج ہم جانتے ہیں کہ ایک ارتقا پذیر ادارہ ہے۔ اس میں مسلم سماج کا کوئی استثنا نہیں۔ اس ارتقا نے کئی نئے سماجی اداروں کو جنم دیا اور سماج کی ایک نئی تشکیل سامنے آئی۔ علم‘ سیاست‘ معیشت اور دعوت واصلاح کے امور‘ جو کبھی ایک قیادت کے تحت سرانجام پاتے تھے‘ اب مختلف طبقات میں تقسیم ہو گئے۔ سیاسی آرا کو منظم کر نے کے لیے سیاسی جماعتیں قائم ہوئیں۔ علمی ادارے بنائے گئے۔ معاشی ادارے بنے۔ مسلم سماج میں دعوت کا کام بھی علما ہی کرتے تھے کہ دعوت علم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بعد میں مگر علمی تحقیق اور دعوت الگ ہو گئے۔ تحقیق کے لوگ عوام سے کٹ گئے کہ تحقیق خلوت پسند ہے۔ اب کچھ لوگوں نے دین کی بنیادی باتوں کو جانا اور انہیں عام آدمی تک پہنچانا شروع کیا۔ سول سوسائٹی منظم ہوئی تو مذہبی اصلاحی جماعتیں بھی بننے لگیں۔ ان کو قائم کرنے والے وہی لوگ تھے جو مزاجاً جلوت پسند تھے۔
دورِ جدید میں اسلام کے سیاسی غلبے کو مقاصدِ دین میں شامل کیا گیا تو اس کے لیے مذہبی سیاسی جماعتیں قائم کی گئیں۔ یہ عام سیاسی جماعتوں کی طرح‘ سیاسی تبدیلی کے لیے سرگرم سرگروہ تھے جن کا منشور اسلام کی تعلیمات پر مبنی تھا۔ ماضی میں بھی علما نے مذہبی جماعتیں بنائیں مگر وہ ایک بڑے مقصد‘ آزادی کے لیے تھیں اور انہوں نے غیر مذہبی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر سیاسی جدوجہد کی۔ اس کے لیے برصغیر اور انڈونیشیا جیسے مسلم ممالک میں اُٹھنے والی آزادی کی تحریکوں کو سمجھنا چاہیے۔
اس عمل سے سماجی اور سیاسی سطح پر ایک نیا طبقہ سامنے آیا جو مذہب کے نام پر سرگرم تھا۔ اسے 'مذہبی قیادت‘ کہا گیا۔ یہ علما سے مختلف ایک طبقہ ہے جسے سماجی ارتقا نے وجود بخشا۔ یہ معروف معنوں میں عالمِ دین نہیں ہیں لیکن سیاست اور سماج کی مذہبی تشکیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ روایتی اعتبار سے ایسا کوئی طبقہ مسلم سماج میں موجود نہیں تھا۔ یہ سیاسی وسماجی گروہ علما نے قائم کیے لیکن وقت کے ساتھ‘ یہ ان کی گرفت سے آزاد ہو گئے۔ جیسے جماعت اسلامی‘ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے قائم کی مگر آج اس کی قیادت میں سراج الحق صاحب‘ نعیم الرحمن صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب بھی شامل ہیں۔ یا جمعیت علمائے اسلام کو دیوبندی علمانے وجود بخشا مگر اب اس کی قیادت میں اکرم درانی صاحب اور غلام علی صاحب کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ دینی اعتبار سے کیا اس طبقے کو علما پر قیاس کیا جائے گا؟
میرا جواب نفی میں ہے۔ میرے نزدیک جو سیاست میں سرگرم ہیں‘ وہ اصلاً سیاستدان ہیں۔ اس لیے انہیں سیاستدانوں میں شامل کیا جانا چاہیے۔ جو سماجی فلاح یا تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں‘ انہیں سول سوسائٹی کے اداروں میں شامل کیا جائے جیسے دینی مدارس۔ ہمارے ہاں اسی وجہ سے دینی مدارس سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت قائم ہوتی ہیں جس کے تحت دیگر این جی اوز رجسٹر ہوتی ہیں۔ ایک درجے میں اس کا شعور ان لوگوں میں موجود ہے جو ان اداروں سے وابستہ ہیں۔ اس لیے وہ سیاسی وابستگی کے باوجود خود کو غیر سیاسی کہتے ہیں۔
سماجی سطح پر مگر ایک ابہام موجود ہے۔ جب 'مذہبی قیادت‘ کی بات ہوتی ہے تو اس میں علما سمیت یہ سب طبقات شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ طے کرنا مشکل ہو جا تا ہے کہ کس کا کیا کام ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ علما کا کام سیاست نہیں ہے‘ تو پھر یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ سیاست کیا علما کے لیے حرام ہے؟ سوال حرام حلال کا نہیں‘ سماجی نظم کا ہے۔ جب مدرسے کو ایک ایسے قانون کے تحت رجسٹر کرایا جاتا ہے جو تعلیم یا تربیت کے لیے وقف ہے تو وہ قانوناً پابند ہو جاتا ہے کہ سیاست سے دور رہے۔ بالکل اسی اصول پر جس اصول کے تحت ایک این جی او کو یہ حق نہیں کہ وہ سیاست میں حصہ لے۔ جس کو سیاست میں حصہ لینا ہے‘ اسے کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے جو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹر ہوتی ہے۔
علما اور جدید مذہبی قیادت کے اس فرق کو نہ سمجھنے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جو فتویٰ یا رائے دینے کا اہل نہیں‘ وہ مذہب کے نام پر لوگوں کے قتل کا فتویٰ جاری کر رہا ہوتا ہے اور اپنی شعلہ بیانی سے مذہبی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس طبقے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ سیاسی جماعت ہیں؟ اگر ہیں تو قتل کا فتویٰ ان کا کام نہیں۔ اگر وہ این جی او ہیں تو بھی یہ حدود سے تجاوز ہے۔ اگر علما کی نمائندگی کرتے ہیں تو علما کا کام جلوس برآمد کرنا یا سماج میں اشتعال پھیلانا نہیں۔
مسلم سماج میں علما کا کردار ہمیشہ باوقار رہا ہے۔ عام آدمی ان کے علم‘ تدین‘ اخلاق اور خدا ترسی کے باعث ان کا احترام کرتا ہے۔ نئی وجود میں آنے والی مذہبی قیادت نے اسلام اور علما کے لیے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے علما بھی مطعون ہوتے ہیں۔ علما کو اپنے وقار کی حفاظت کے لیے اپنا تشخص برقرار رکھنا ہو گا۔ انہیں ایسے لوگوں سے فاصلہ پیدا کرنا چاہیے جو مذہب کو سیاسی اور دیگر سماجی ومعاشی فوائد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ فاصلہ واضح ہو جائے تو علما کا سماجی کردار نکھر کر سامنے آئے گا جس میں سب کی بھلائی ہے۔ علما کی بھی اور عوام کی بھی۔ حکومت کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔ اس نے دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جنہیں مذہب کا نمائندہ مانا جائے۔ جب مذہب کے نام پر متحرک ہر آدمی کو 'مذہبی قیادت‘ کے عنوان سے اقتدار کے ایوانوں میں تکریم دی جاتی ہے تو عوام انہیں اپنا مذہبی راہنما سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مذہب کی باگ علما کے ہاتھ سے نکل کر ان گروہوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو ریاست‘ سماج‘ مذہب اور عوام کے لیے مسائل کا باعث بنتے ہیں۔