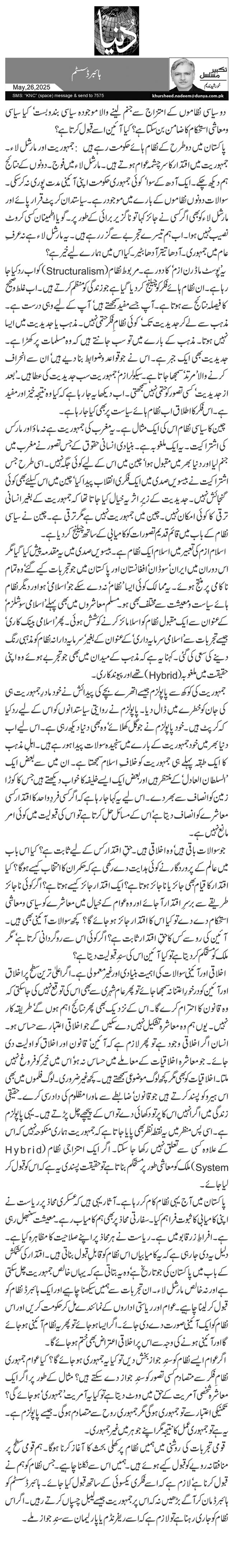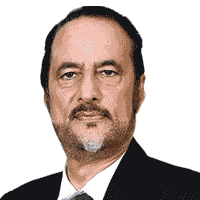ہائبرڈ سسٹم
دو سیاسی نظاموں کے امتزاج سے جنم لینے والا موجودہ سیاسی بندوبست‘ کیا سیاسی ومعاشی استحکام کا ضامن بن سکتا ہے؟ کیا آئین اسے قبول کرتا ہے؟
پاکستان میں دو طرح کے نظام ہائے حکومت رہے ہیں: جمہوریت اور مارشل لاء۔ جمہوریت میں اقتدار کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں۔ مارشل لاء میں فوج۔ دونوں کے نتائج ہم دیکھ چکے۔ ایک آدھ کے سوا‘ کوئی جمہوری حکومت اپنی آئینی مدت پوری نہ کر سکی۔ سوالات دونوں نظاموں کے بارے میں موجود رہے۔ سیاستدان کرپٹ قرار پائے اور مارشل لاء کو بھی اگر کسی نے جائز کہا تو ناگزیر برائی کے طور پر۔ گویا اطمینان کسی کروٹ نصیب نہیں ہوا۔ اب ہم تیسرے تجربے سے گزر رہے ہیں۔ یہ مارشل لاء ہے نہ عرفِ عام میں جمہوری۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ کیا اس میں ہمارے لیے خیر ہے؟
یہ 'پوسٹ ماڈرن ازم‘ کا دور ہے۔ مربوط نظام (Structuralism) کو اب رد کیا جا رہا ہے۔ ان نظام ہائے فکر کو چیلنج کر دیا گیا ہے جو زندگی کو منظم کرتے ہیں۔ اب غلط وصحیح کا فیصلہ نتائج سے ہوتا ہے۔ آپ جسے مفید سمجھتے ہیں‘ آپ کے لیے وہی درست ہے۔ مذہب سے لے کر جدیدیت تک‘ کوئی نظامِ فکر حتمی نہیں۔ مذہب یا جدیدیت میں ایسا نہیں ہوتا۔ مذہب کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ مسلمات پر کھڑا ہے۔ جدیدیت بھی ایک جبر ہے۔ اس نے جو قواعد وضوابط بنا دیے ہیں‘ ان سے انحراف کرنے والا 'مرتد‘ سمجھا جاتا ہے۔ سیکولرازم‘ جمہوریت سب جدیدیت کی عطا ہیں۔ 'بعد از جدیدیت‘ کسی تصور کوحتمی نہیں سمجھتی۔ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیا وہ نتیجہ خیز اور مفید ہے۔ اس فکر کا اطلاق اب نظام ہائے سیاست پر بھی کیا جا رہا ہے۔
چین کا سیاسی نظام اس کی ایک مثال ہے۔ یہ مغرب کی جمہوریت ہے نہ ماؤ اور مارکس کی اشتراکیت۔ یہ ایک ملغوبہ ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کے جس تصور نے مغرب میں جنم لیا اور دنیا بھر میں مقبول ہوا‘ چین میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اسی طرح جس اشتراکیت نے بیسویں صدی میں ایک فکری انقلاب پیدا کیا‘ چین میں اس کیلئے بھی کوئی گنجائش نہیں۔ جدیدیت کے زیرِ اثر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جمہوریت کے بغیر انسانی ترقی کا کوئی امکان نہیں۔ چین میں جمہوریت نہیں ہے مگر ترقی ہے۔ چین نے سیاسی نظام کے باب میں قائم قدیم تصورات کو کامیابی کے ساتھ چیلنج کر دیا ہے۔
اسلام ازم کی تعبیر میں اسلام ایک نظام ہے۔ بیسویں صدی میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا مگر اس دوران میں ایران‘ سوڈان‘ افغانستان اور پاکستان میں جو تجربات کیے گئے‘ وہ تمام ناکامی پر منتج ہوئے۔ یہ ممالک کوئی ایسا 'نظام‘ نہ دے سکے جو 'اسلامی‘ ہو اور دیگر نظام ہائے سیاست ومعیشت سے مختلف بھی ہو۔ مسلم معاشروں میں بھی پہلے 'اسلامی سوشلزم‘ کے عنوان سے ایک مقبول نظام کو اسلامائز کرنے کوشش ہوئی۔ پھر 'اسلامی بینک کاری‘ جیسے تجربات سے 'اسلامی سرمایہ داری‘ کے عنوان کے بغیر‘ سرمایہ دارانہ نظام کو مذہبی رنگ دینے کی سعی کی گئی۔ کہنا یہ ہے کہ مذہب کے میدان میں بھی جو تجربے ہوئے وہ اپنی حقیقت میں ملغوبہ (Hybrid) تھے اور پیوند کاری۔
جمہوریت کی کوکھ سے پاپولزم جیسے اتھرے بچے کی پیدائش نے خود مادرِ جمہوریت ہی کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ پاپولزم نے روایتی سیاستدانوں کو اس کے لیے رد کیا کہ کرپٹ ہیں۔ خود پاپولزم نے جو گل کھلائے‘ وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس لیے اب دنیا بھر میں خود جمہوریت کے بارے میں سنجیدہ سولات پیدا ہو رہے ہیں۔ اہلِ مذہب کا ایک طبقہ پہلے ہی جمہوریت کو خلافِ اسلام سمجھتا ہے۔ ان میں سے بعض ایک 'السلطان العادل‘ کے منتظر ہیں اور بعض ایک ایسے خلیفہ کا خواب دیکھتے ہیں جس کا کوڑا زمین کو انصاف سے بھر دے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی فردِ واحد کا اقتدار کسی معاشرے کو انصاف دیتا ہے‘ اس کے مسائل حل کرتا ہے تو اس کی قبولیت میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔
جو سوالات باقی ہیں‘ وہ اخلاقی ہیں۔ حقِ اقتدار کس کے لیے ثابت ہے؟ کیا اس باب میں عالم کے پروردگار نے کوئی ہدایت دے رکھی ہے کہ حکمران کا انتخاب کیسے ہو گا؟ کیا اقتدار کا قیام بھی جائز یا ناجائز ہوتا ہے؟ ایک اقتدار جائز کیسے ہوتا ہے؟ اگر کوئی ناجائز طریقے سے برسرِ اقتدار آ جائے اور وہ عوام کے خیال میں معاشرے کو سیاسی ومعاشی استحکام دے دے تو کیا اس کا اقتدار جائز ہو جائے گا؟ کچھ سوالات آئینی بھی ہیں۔ آئین کی رو سے کس کا حقِ اقتدار ثابت ہے؟ اگر کوئی اس سے روگردانی کرتا ہے‘ مگر ملک کو مستحکم کر دیتا ہے تو کیا آئین اس کی سندِ قبولیت دیتا ہے؟
اخلاقی اور آئینی سوالات کی اہمیت بنیادی اور غیر معمولی ہے۔ اگر اعلیٰ ترین سطح پر اخلاق اور آئین کو درخورِ اعتنا نہ سمجھا جائے تو پھر عام شہری سے بھی اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ قانون کا احترام کرے گا۔ اس کے نزدیک بھی پھر نتائج اہم ہوں گے‘ طریقہ کار نہیں۔ یوں ہم وہ معاشرہ تشکیل نہیں دے سکیں گے جو اخلاقی اعتبار سے حساس ہو۔ انسان اگر اخلاقی وجود ہے تو پھر لازم ہے کہ آئین‘ قانون اور اخلاق کو اولیت دی جائے۔ جو معاشرہ اخلاقیات کے معاملے میں حساس نہ ہو‘ اس میں خیر کو فروغ نہیں ملتا۔اخلاقیات کو بھی مگر کچھ لوگ موضوعی سمجھتے ہیں۔ کچھ غیر ضروری۔ لوگ فلموں میں بھی اس ہیرو کو پسند کرتے ہیں جو قانون‘ ضابطے سے ماورا مظلوم کی داد رسی کرے۔ حقیقی زندگی میں اگر انہیں اس کا پرتو دکھائی دے تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہی پاپولزم ہے۔ اسی پس منظر میں یہ نقطہ نظر بھی پایا جاتا ہے کہ جمہوریت ہماری منکوحہ نہیں کہ اس کے علاوہ کسی سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر ایک امتزاجی نظام (Hybrid System) ملک کو معاشی طور پر مستحکم بناتا ہے تو حقیقت پسندی یہ ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔
پاکستان میں آج یہی نظام کام کر رہا ہے۔ آثار یہی ہیں کہ عسکری محاذ پر ریاست نے اپنی کامیابی کا ثبوت فراہم کیا۔ سفارتی محاذ پر بھی ہم کامیاب رہے۔ معیشت سنبھل رہی ہے۔ افراطِ زر قابو میں ہے۔ ریاست نے ہر محاذ پر اپنے صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ یہ کامیابیاں اس نظام کو قابلِ قبول بناتی ہیں۔ اقتدار کی کشمکش کے باب میں پاکستان کی جو تاریخ ہے‘ وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں خالص جمہوریت چل سکتی ہے اور نہ خالص مارشل لاء۔ ان تجربات سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ایک ہائبرڈ نظام کو قبول کر لینا چاہیے۔ عوام اور ریاستی اداروں کے نمائندے مل کر حکومت کریں اور اس نظام کو ایک آئینی صورت دے دی جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ نظام آئینی ہو جائے گا اور آئینی ہونے کی وجہ سے اس پر اخلاقی اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔
اگر عوام ایسے نظام کو سندِ جواز بخش دیں تو کیا یہ جمہوری ہو جائے گا؟ کیا عوام جمہوری نظامِ فکر سے متصادم کسی تصور کو سندِ جواز دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر ایک معاشرہ شخصی آمریت کے حق میں ووٹ دیتا ہے توکیا یہ آمریت 'جمہوری‘ ہو جائے گی؟ تکنیکی اعتبار سے تو جمہوری ہو گی مگر جمہوری روح سے متصادم ہو گی۔ جیسے پاپولزم ہے۔ یہ ہے تو جمہوری عمل کا نتیجہ مگر اپنے جوہر میں غیر جمہوری۔
قومی تجربات کی روشنی میں ہمیں نظام پر کھلی بحث کا آغاز کرنا ہوگا۔ ہم قومی سطح پر منافقانہ رویے کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ جس نظام کو ہم نے قبول کرنا ہے‘ لازم ہے کہ اسے فکری یکسوئی کے ساتھ قبول کیا جائے۔ ہائبرڈ سسٹم کو ہائبرڈ مان کر آگے بڑھیں نہ کہ اس پر جمہوریت جیسے لیبل چسپاں کرتے رہیں۔ اگر اس نظام کو جاری رہنا ہے تو لازم ہے کہ اسے ریفرنڈم یا پارلیمان سے سندِ جواز ملے۔