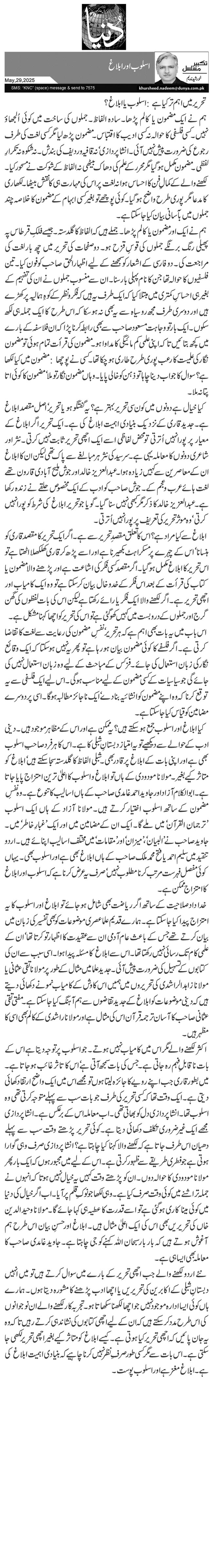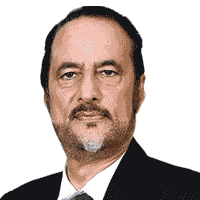اسلوب اور ابلاغ
تحریر میں اہم تر کیا ہے: اسلوب یا ابلاغ؟
ہم نے ایک مضمون یا کالم پڑھا۔ سادہ الفاظ۔ جملوں کی ساخت میں کوئی اُلجھاؤ نہیں۔ کسی فلسفی کا حوالہ نہ کسی ادیب کا اقتباس۔ مضمون پڑھ لیا مگر کسی لغت کی طرف رجوع کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ انشا پردازی‘ نہ قافیہ و ردیف کی بندش۔ نہ شکوہ نہ تکرارِ لفظی۔ مضمون مکمل ہو گیا مگر محرر کے علم کی دھاک بیٹھی نہ الفاظ کے شوکت نے مسحور کیا۔ لکھنے والے کے کمالِ فن کا احساس ہوا نہ لغت پر اس کی مہارت ہی کا نقش بیٹھا۔ لکھاری کا مدعا مگر پوری طرح واضح ہو گیا۔ کوئی پوچھے تو بغیر کسی ابہام کے مضمون کا خلاصہ چند جملوں میں بآسانی بیان کیا جا سکتا ہے۔
ہم نے ایک اور مضمون یا کالم پڑھا۔ جملے ہیں کہ الفاظ کا گلدستہ۔ جیسے فلکِ قرطاس پہ پھیلی رنگ برنگے جملوں کی قوسِ قزح ہو۔ دو صفحات کی تحریر میں چھ بار لغت کی مراجعت کی۔ دو فارسی کے اشعار کو سمجھنے کے لیے اظہارالحق صاحب کو فون کیا۔ تین فلسفیوں کا حوالہ تھا جن کا نام پہلی بار سنا۔ ان سے منسوب جملوں نے ان کی تفہیم کے بغیر ہی احساسِ کمتری میں مبتلا کیا کہ ایک طرف یہ ہیں کہ فکر و نظر کے کوہِ ہمالیہ پر کھڑے ہیں اور دوسری طرف مجھ رو سیاہ سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ اس طرح کا ایک جملہ ہی لکھ سکوں۔ ایک بار تو وجاہت مسعود صاحب سے بھی رابطہ کرنا پڑا کہ ان فلاسفہ کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ اپنی علمی کم مائیگی کا مداوا ہو۔ مضمون کی قرأت تمام ہوئی تو مضمون نگار کی علمیت کا رعب پوری طرح طاری ہو چکا تھا۔ کسی نے پوچھا: مضمون میں کیا لکھا ہے؟ سوال کا جواب دینا چاہا تو ذہن کو خالی پایا۔ وہاں مضمون نگار تو ملا‘ مضمون کا کوئی اتا پتا نہ ملا۔
کیا خیال ہے دونوں میں کون سی تحریر بہتر ہے؟ یہ گفتگو ہو یا تحریر‘ اصل مقصد ابلاغ ہے۔ جدید قاری کے نزدیک بنیادی اہمیت ابلاغ کی ہے۔ ایک تحریر اگر ابلاغ کے معیار پر پورا نہیں اُترتی تو محض لفاظی اسے ایک اچھی تحریر ثابت نہیں کرتی۔ نثر اور شاعری دونوں کا معاملہ یہی ہے۔ سر سید کی نثر ہر مبالغے سے پاک تھی لیکن ان کا ابلاغ ان کے معاصرین سے کہیں زیادہ ہوا۔ عبدالعزیز خالد اور جوش ملیح آبادی قارون تھے لغت ہائے عرب و عجم کے۔ جوش صاحب کو ادب کے ایک مخصوص حلقے نے زندہ رکھا ہے۔ عبدالعزیز خالد کا ذکر مگر کبھی نہیں سنا گیا۔ گویا جو تحریر ابلاغ کی شرط کو پورا نہیں کرتی‘ وہ موثر تحریر کی تعریف پر پورا نہیں اُترتی۔
ابلاغ سے کیا مراد ہے؟ اس کا تعلق مقصدِ تحریر سے ہے۔ اگر ایک تحریر کا مقصد قاری کو ہنسانا‘ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا ہے اور اسے پڑھ کر قاری کھلکھلا اٹھتا ہے تو اس تحریر کا ابلاغ مکمل ہو گیا۔ اگر مقصدکسی فکر کی اشاعت ہے اور پڑھنے والا مضمون یا کتاب کی قرأت کے بعد اس فکر کے خدو خال بیان کر سکتا ہے تو وہ ایک کامیاب اور اچھی تحریر ہے۔ اگر لکھنے والا ایک فکر یا رائے رکھتا ہے لیکن اس کی بات لفظوں کی گھن گرج اور جملوں کے در و بست میں کہیں کھو گئی ہے تو اس کی تحریر کو اچھا کہنا مشکل ہے۔
اس باب میں یہ بات بھی اہم ہے کہ ہر تحریر‘ نفسِ مضمون کی رعایت سے لغت کا تقاضا کر تی ہے۔ اگر فلسفے کا کوئی مضمون بیان ہو رہا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقائع نگارکی زبان استعمال کی جائے۔ فزکس کے مباحث کے لیے وہ زبان استعمال نہیں کی جائے گی جو سیاسیات کے کسی مضمون کے لیے مناسب ہو گی۔ اس لیے ایک فلسفی سے یہ توقع کرنا کہ وہ اپنے مضمون کو انشائیہ بنا دے‘ ایک ناجائز مطالبہ ہو گا۔ اسی پر دوسرے مضامین کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔
کیا ابلاغ اور اسلوب جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے اور اس کے مظاہر موجود ہیں۔ دینی ادب کے حوالے سے دیکھیے تو یہ امتیاز دبستانِ شبلی کا ہے۔ اس کا ہر فرد صاحبِ اسلوب بھی ہے اور اپنی بات کے ابلاغ پر قادر بھی۔ شبلی الفاظ کا گلدستہ سجا سکتے ہیں‘ ابلاغ کو متاثر کیے بغیر۔ مولانا مودودی کے ہاں تو ابلاغ و اسلوب کا اعلیٰ ترین امتزاج پایا جاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد اور جاوید احمد غامدی صاحب کے ہاں اسالیب کا تنوع ہے۔ وہ نفسِ مضمون کے ساتھ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ مولانا آزاد کے ہاں ایک اسلوب 'ترجمان القرآن‘ میں ملے گا۔ ایک ان کے مضامین میں اور ایک 'غبارِ خاطر‘ میں۔ جاوید صاحب نے 'البیان‘، 'میزان‘ اور 'مقامات‘ میں مختلف اسالیب اپنائے ہیں۔ اردو تنقید میں سلیم احمد یا فتح محمد ملک صاحب کے ہاں ابلاغ بھی ہے اور اسلوب بھی۔ یہاں کوئی مفصل فہرست مرتب کرنا مطلوب نہیں‘ صرف یہ عرض کر نا ہے کہ اسلوب اور ابلاغ کا امتزاج ممکن ہے۔
خدا داد صلاحیت کے ساتھ اگر ریاضت بھی شامل ہو جائے تو ابلاغ اور اسلوب کا یہ امتزاج پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے قدیم علما عصری موضوعات کو بھی تفسیر کی زبان میں بیان کرتے تھے جس کے باعث عام آدمی ان سے عقیدت کا اظہار تو کرتا تھا‘ ان کے علمی کام تک رسائی نہیں رکھتا تھا۔ اس سے ابلاغ کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اسی سبب سے ان کی کتابوں کے تسہیل کی ضرورت پیش آئی۔ جدید علما میں مثال کے طور پر مولانا تقی عثمانی یا مولانا زاہد الراشدی کی تحریروں میں ہمیں اس کاوش کے کامیاب نمونے دکھائی دیتے ہیں کہ دینی موضوعات کو ابلاغ کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن اس کی مثال ہے اور مولانا راشدی کے کالم بھی اسی کا مظہر ہیں۔
اکثر لکھنے والے مگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ جو اسلوب پر توجہ دیتا ہے اس کے بات ناقابلِ فہم رہ جاتی ہے۔ جس کی بات سمجھ آتی ہے‘ اس کا تاثر غائب ہو جاتا ہے۔ میں بطور قاری جب اپنے رویے کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے اس میں ایک واضح ارتقا دکھائی دیتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ کسی تحریر کی طرف جو بات سب سے پہلے متوجہ کرتی تھی وہ اسلوب تھا۔ انشا پردازی دل کو بھاتی تھی۔ اب معاملہ اس کے برعکس ہے۔ انشا پردازی مجھے ایک غیرضروری تکلف دکھائی دیتا ہے۔ کوئی تحریر پڑھتے وقت سب سے پہلے دھیان اس طرف جاتا ہے کہ لکھنے والا کہنا کیا چاہتا ہے؟ انشا پردازی صرف وہی گوارا ہوتی ہے جو فطری طریقے سے ظہور کرتی ہے۔ اس کے لیے میں مجبور ہوں کہ ایک بار پھر مولانا مودودی کا حوالہ دوں۔ ان کو پڑھتے وقت کہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ انہوں نے جملہ تراشنے میں کوئی وقت صرف کیا ہے۔ وہی لکھا جو نوکِ قلم پر آیا۔ اب اگر خیال کی دنیا میں کوئی مینا کاری ہو گئی ہے تو اسے قدرت کا عطیہ ہی کہا جائے گا۔ مولانا وحید الدین خاں کی تحریریں بھی اس کی ایک اعلیٰ مثال ہیں۔ ابلاغ اور حسنِ بیان اس طرح ہم آغوش ہو تے ہیں کہ بار بار سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ جاوید غامدی صاحب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔
نئے اردو لکھنے والے جب اچھی تحریر کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں انہیں دبستانِ شبلی کے اکابرین کی تحریریں یا اچھا ادب پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں جو اچھا لکھنا سکھاتا ہو۔ تجربہ کار لکھنے والے ان نوجوانوں کی اس طرح مدد کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے اچھی کتابوں کی نشاندہی کرتے رہیں تاکہ وہ یہ جان پائیں کہ اچھی تحریر کیا ہو تی ہے۔ کیسے ابلاغ کو متاثر کیے بغیر اچھی تحریر لکھی جا سکتی ہے۔ اس بات سے مگر کسی طور صرفِ نظر نہیں کرنا چاہیے کہ بنیادی اہمیت ابلاغ کی ہے۔ ابلاغ مغز ہے اور اسلوب پوست۔