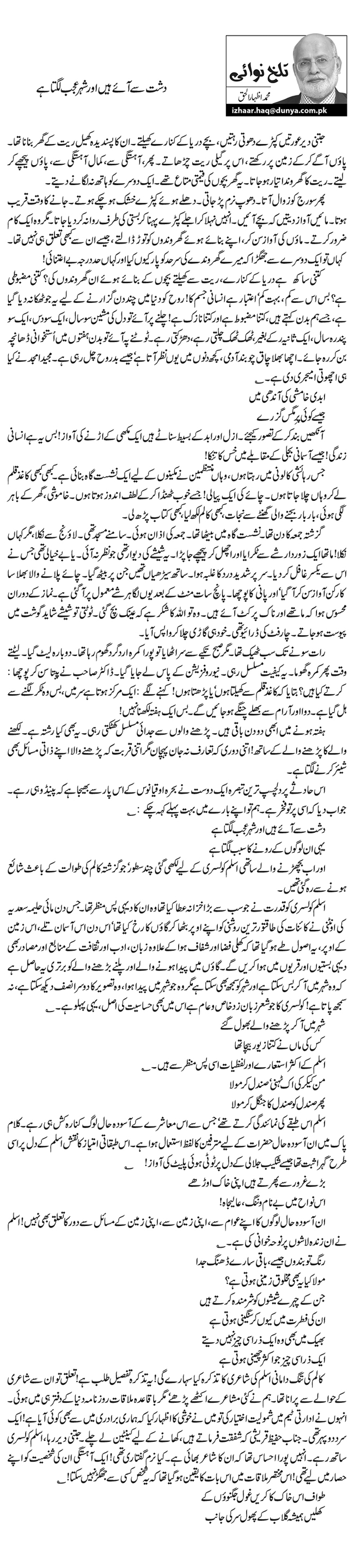تاریخ اشاعت 2016-11-25
دشت سے آئے ہیں اور شہر عجب لگتا ہے
جتنی دیر عورتیں کپڑے دھوتی رہتیں، بچے دریا کے کنارے کھیلتے۔ ان کا پسندیدہ کھیل ریت کے گھر بنانا تھا۔ پائوں آگے کرکے زمین پر رکھتے، اس پر گیلی ریت چڑھاتے۔ پھر، آہستگی سے، کمال آہستگی سے، پائوں پیچھے کر لیتے۔ ریت کا گھروندا تیار ہو جاتا۔ یہ گھر بچوں کی قیمتی متاع تھے۔ ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگانے دیتے۔
پھر سورج کو زوال آتا۔ دھوپ نرم پڑ جاتی۔ دھلے ہوئے کپڑے خشک ہو چکے ہوتے۔ جانے کا وقت قریب ہوتا۔ مائیں آواز دیتیں کہ بچے آئیں۔ انہیں نہلا کر اجلے کپڑے پہنا کر بستی کی طرف روانہ کر دیا جاتا۔ مگر وہ ایک کام ضرور کرتے۔ مائوں کی آواز سن کر، اپنے بنائے ہوئے گھروندوں کو توڑ ڈالتے، جیسے ان سے کبھی تعلق ہی نہیں تھا۔ کہاں تو ایک دوسرے سے جھگڑا کہ میرے گھروندے کی سرحد کو پار کیوں کیا اور کہاں حد درجہ بے اعتنائی!
کتنی ساکھ ہے دریا کے کنارے، ریت سے کھیلتے بچوں کے بنائے ہوئے ان گھروندوں کی؟ کتنی مضبوطی ہے؟ بس اس سے کم، بہت کم‘ اعتبار ہے انسانی جسم کا! روح کو دنیا میں چند دن گزارنے کے لیے یہ جو ٹھکانہ دیا گیا ہے، جسے ہم بدن کہتے ہیں، کتنا مضبوط ہے اور کتنا نازک ہے! چلنے پر آئے تو دل کی مشین سو سال، ایک سو دس، ایک سو پندرہ سال، ایک ثانیہ رکے بغیر، ٹھک ٹھک چلتی رہے، دھڑکتی رہے۔ ٹوٹنے پہ آئے تو بدن ہفتوں میں اُستخوانی ڈھانچہ بن کر رہ جائے۔ اچھا بھلا چاق چوبند آدمی، کچھ دنوں میں یوں نظر آتا ہے‘ جیسے بدروح چل رہی ہے۔ مجید امجد نے کیا ہی اچھوتی امیجری دی ہے۔؎
ابدی خامشی کی آندھی میں
جیسے کوئی پرِ مگس گزرے
آنکھیں بند کرکے تصور کیجئے۔ ازل اور ابد کے بسیط سناٹے ہیں ایک مکھی کے اڑنے کی آواز! بس یہ ہے انسانی زندگی! جیسے آسمانی بجلی کے مقابلے میں خس کا تنکا!
جس رہائشی کالونی میں رہتا ہوں، وہاں منتظمین نے مکینوں کے لیے ایک نشست گاہ بنائی ہے۔ کبھی کبھی کاغذ قلم لے کر وہاں چلا جاتا ہوں۔ چائے کی ایک پیالی! جسے خوب ٹھنڈا کرکے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ خاموشی، گھر کے باہر لگی ہوئی، بار بار بجنے والی گھنٹے سے نجات، کبھی کالم لکھ لیا، کبھی کتاب پڑھ لی۔
گزشتہ جمعہ کا دن تھا۔ نشست گاہ میں بیٹھا تھا۔ جمعہ کی اذان ہوئی۔ سامنے مسجد تھی۔ لائونج سے نکلا، مگر کہاں نکلا! ماتھا ایک زوردار شے سے ٹکرایا اور اچھل کر پیچھے جا پڑا۔ یہ شیشے کی دیوار تھی جو نظر نہ آئی۔ یا بے خیالی تھی جس نے اس سے یکسر غافل کر دیا۔ سر پر شدید درد کا غلبہ ہوا۔ ساتھ سیڑھیاں تھیں جن پر بیٹھ گیا۔ چائے پلانے والا بھلا سا کارکن آواز سن کر آ گیا‘ اور پانی کا پوچھا۔ پانچ سات منٹ کے بعد یوں لگا ہر شے معمول پر آ گئی ہے۔ نماز کے دوران محسوس ہوا کہ ماتھے اور ناک پر کٹ آئے ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ عینک بچ گئی۔ ٹوٹتی تو شیشے شاید گوشت میں پیوست ہو جاتے۔ چار فٹ کی ڈرائیو تھی۔ خود ہی گاڑی چلا کر واپس آیا۔
رات سونے تک سب ٹھیک تھا۔ مگر صبح تکیے سے سر اٹھایا تو پورا کمرہ اردگرد گھوم رہا تھا۔ دوبارہ لیٹ گیا۔ لیٹتے وقت پھر کمرہ گھوما۔ یہ کیفیت مسلسل رہی۔ نیوروفزیشن کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پبتا سن کر پوچھا: کرتے کیا ہیں؟ بتایا کہ کاغذ قلم سے کھیلتا ہوں‘ یا پڑھتا ہوں! کہنے لگے: ایک مرکز ہوتا ہے سر میں، بس وہ ٹکر لگنے سے ہل گیا ہے۔ دوا اور آرام سے بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ بس ایک ہفتہ لکھنا نہیں!
ہفتہ ہونے میں ابھی دو دن باقی ہیں۔ پڑھنے والوں سے جدائی مسلسل کھٹکتی رہی۔ یہ بھی کیا رشتہ ہے۔ لکھنے والے کا پڑھنے والے کے ساتھ! اتنی دوری کہ تعارف نہ جان پہچان مگر اتنی قربت کہ پڑھنے والا اپنے ذاتی مسائل بھی شیئر کرنے لگتا ہے۔
اس حادثے پر دلچسپ ترین تبصرہ ایک دوست نے بحرہ اوقیانوس کے اس پار سے بھیجا ہے کہ پینڈو ہی رہے۔ جواب دیا کہ اسی پر تو فخر ہے۔ ہم تو اپنے بارے میں بہت پہلے کہہ چکے: ؎
دشت سے آئے ہیں اور شہر عجب لگتا ہے
یہی ان لوگوں کے رونے کا سبب لگتا ہے
اور اب بچھڑنے والے ساتھی اسلم کولسری کے لیے لکھی گئی چند سطور‘ جو گزشتہ کالم کی طوالت کے باعث شائع ہونے سے رہ گئی تھیں۔
اسلم کولسری کو قدرت نے جو سب سے بڑا خزانہ عطا کیا تھا وہ ان کا دیہی پس منظر تھا۔ جس دن مائی حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی نے کائنات کی طاقتور ترین روشنی کو اپنے اوپر بٹھا کر گائوں کا رخ کیا تھا‘ اس دن اس آسمان تلے، اس زمین کے اوپر، یہ اصول طے ہو گیا تھا کہ کھلی فضا اور شفاف ہوا کے علاوہ زبان، ادب اور ثقافت کے منابع اور مصادر بھی دیہی بستیوں اور قریوں میں ہوا کریں گے۔ گائوں میں پیدا ہونے والے اور پلنے بڑھنے والے کو برتری یہ حاصل ہے کہ وہ شہر میں آ کر بس سکتا ہے اور شہر کو سمجھ بھی سکتا ہے مگر وہ جو شہر میں پیدا ہوا، وہ تصویر کا دوسرا نصف دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھ پاتا ہے! کولسری کا جو شعر زبان زد خاص و عام ہے اس میں بھی حساسیت کی اصل، یہی پہلو ہے۔؎
شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے
کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا
اسلم کے اکثر استعارے اور لفظیات اسی پس منظر سے ہیں۔؎
من کیکر کی اک ٹہنی‘ صندل کر مولا
پھر صندل کو صندل کا جنگل کر مولا
اسلم اس طبقے کی نمائندگی کرتے تھے‘ جس سے اس معاشرے کے آسودہ حال لوگ کنارہ کش ہی رہے۔ کلام پاک میں ان آسودہ حال حضرات کے لیے مترفین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس طبقاتی امتیاز کا نقش اسلم کے دل پر اسی طرح گہرا ثبت تھا جیسے شکیب جلالی کے دل پر ٹوٹی ہوئی پلیٹ کی آواز! ؎
بڑے غرور سے پھرتے ہیں اپنی خاک اوڑھے
اس نواح میں بے نام و ننگ، عالیجاہ!
ان آسودہ حال لوگوں کا اپنے عوام سے، اپنی زمین سے، اپنی زمین کے مسائل سے دور کا تعلق بھی نہیں! اسلم نے ان زندہ لاشوں پر نوحہ خوانی کی ہے۔؎
رنگ تو بندوں جیسے، باقی سارے ڈھنگ جدا
مولا کیا یہ بھی مخلوق زمینی ہوتی ہے؟
جن کے چہرے شیشوں کو شرمندہ کرتے ہیں
ان کی فطرت میں کیوں کر سنگینی ہوتی ہے
بھیک میں بھی وہ ایک ذرا سی چیز نہیں دیتے
ایک ذرا سی چیز جو اکثر چھینی ہوتی ہے
کالم کی تنگ دامانی اسلم کی شاعری کا تذکرہ کیا سہارے گی! یہ تذکرہ تفصیل طلب ہے! تعلق تو ان سے شاعری کے حوالے سے پرانا تھا۔ ہم نے کئی مشاعرے اکٹھے پڑھے‘ مگر باقاعدہ ملاقات روزنامہ دنیا کے دفتر ہی میں ہوئی۔ انہوں نے ادارتی ٹیم میں شمولیت اختیار کی تو میں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہماری برادری میں سے بھی کوئی آیا ہے! ایک سرد دوپہر تھی۔ جناب حفیظ قریشی کہ شفقت فرماتے ہیں، کھانے کے لیے کینٹین لے چلے۔ جتنی دیر رہا، اسلم کولسری ساتھ رہے۔ انہیں پورا احساس تھا کہ ان کا شاعر بھائی ہے۔ کیا نرم گفتاری تھی! ایک آہستگی ان کی شخصیت کو اپنے حصار میں لیے تھی! اس مختصر ملاقات میں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص کسی سے جھگڑ نہیں سکتا!؎
طواف اس خاک کا کریں غول جگنوئوں کے
کھلیں ہمیشہ گلاب کے پھول سر کی جانب
محمد اظہارالحق کے مزید کالمز
قیدی سے ملاقات 2026-02-24 اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ 2026-02-19 فبای الاء ربکما تکذبن 2026-02-17 فریاد! کہ ہم مارے گئے! 2026-02-12 پاکستان 2050ء 2026-02-10 خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!! 2026-02-05 سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب 2026-02-03 بحث نہ کرنے کے طریقے 2026-01-29 انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟ 2026-01-27 اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام 2026-01-20