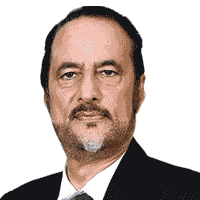انقلاب‘ استعمار وغیرہ
استعمار‘ غلامی‘ آزادی‘ انقلاب‘ امتِ مسلمہ... اَن گنت اصطلاحیں ہیں‘ ہم جن کے حصار میں جیتے ہیں۔ یہ اصطلاحیں اشتراکی نظامِ فکر کی عطا ہیں جو کم وبیش ڈیڑھ سو سال پہلے وجود میں آیا اور ایک صدی پہلے‘ ہمارے فکری ڈھانچے کا حصہ بنا۔ یہ مستعار اصطلاحیں اُس دور کے فکری فیشن کے تحت مقبول ہو گئیں۔ آج یہ فیشن بدل چکا‘ ہم مگر ابھی تک اسے گلے لگائے ہوئے ہیں۔
چند دن پہلے میں نے کالم میں ایرانی مفکر علی شریعتی کا ذکر کیا۔ ایک ذی علم دوست نے توجہ دلائی کہ شریعتی کے ہاں چند ایسے فکری مسائل تھے جن کے سبب ایران کے اہلِ علم میں ان کو پذیرائی مل سکی اور نہ انقلاب کے بعد وہ فکری منظر نامے کاحصہ بن سکے۔ شریعتی انقلابی تھے اور فطری طور پر انقلاب کے بعد ان کے افکار کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو کیوں؟ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریعتی کا بیانیہ بھی دراصل اسی اشتراکی فکر کے زیرِ اثر پروان چڑھا جو اس عہد کا چلن تھا؟
اس نظامِ فکر کو اس دور میں مسلمانوں کے ایک پڑھے لکھے طبقے نے اختیار کیا اور خود کو اس عالمگیر اشترکی تحریک سے وابستہ کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک تصورِ خدا کے اضافے سے اشتراکیت کو مشرف بہ اسلام کیا جا سکتا ہے۔ یہ طبقہ جدید افکار کا فہم رکھتا تھا مگر اسلامی روایت کا نہیں۔ ایک دوسرا طبقہ بھی اس سے متاثر ہوا جو مسلم تہذیبی فضا میں جیتا تھا اور اس میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو دورِ زوال سے نکالنے کا خواہاں تھا۔ اسے یہ ادراک بھی تھا کہ اجتہاد اور تجدید ہی سے اس کا راستہ نکلے گا۔ اس گروہ نے ان اصطلاحوں کو اسلامی لبادہ پہنایا اور اپنی روایت سے امتِ مسلمہ جیسی بعض اصطلاحوں کو لے کر ایک نیا بیانیہ تشکیل دے دیا۔ یہ طبقہ سرخ انقلاب کے بجائے سبز انقلاب کا داعی بن گیا۔
یہ سو برس پر محیط ہماری داستان ہے‘ مغرب میں جس کا آخری باب لکھا جا چکا۔ وہاں اس مزار کے چند مجاور ہی رہ گئے ہیں جنہیں پنپنے کا موقع خود اس سرمایہ دارانہ نظام نے دے رکھا ہے۔ پاکستان میں جن مخلص نوجوانوں نے پھر سے سرخ انقلاب کا پھریرا لہرایا ہے‘ اُن کا سرخیل ان تعلیمی اداروں کا پڑھا ہوا ہے جو سرمایہ داری کی علامت ہیں۔ ان کے اخلاص کا مجھے اعتراف ہے لیکن یہ بے وقت کی راگنی ہے۔ میرا احساس ہے کہ یہ اصطلاحیں ہمارے فکری ارتقا میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ یہ ہمیں ایک ایسے خواب کا اسیر بناتی ہیں جس کی تعبیر دنیا دیکھ چکی۔ لوگوں نے اس کے بعد بھی خواب دیکھے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ جس طرح سو برس پہلے ہم نے انقلاب کا خواب ادھار لیا تھا‘ اب نیا خواب ادھار لیں یا خود کوئی خواب دیکھیں۔
نئے خواب سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں فطرت کی سطح پرکچھ نیا نہیں ہوتا۔ انسان کے فطری خصائص معلوم تاریخ میں ایک طرح کے رہے ہیں۔ طاقت کا کھیل بھی اسی طرح سے جاری ہے۔ اس پہلو سے کچھ نیا نہیں۔ نیا پن ان مسائل کے حل میں ہے‘ آج عالمِ انسانیت جن سے نبرد آزما ہے۔ ان کے بیان کا اسلوب بدل گیا ہے۔ مثال کے طور پر اب بنیادی انسانی حقوق‘ دہشت گردی‘ سول سوسائٹی‘ مکالمہ‘ امن‘ عالمگیریت اور انسانی ترقی جیسی اصطلاحوں میں کلام کیا جاتا ہے۔ یہ اظہار ہے کہ فکرِ انسانی کا فوکس تبدیل ہو گیا ہے۔ اب وہ زندگی کے بعض دوسرے زاویوں کو اہم سمجھنے لگا ہے۔ اس نظامِ فکر میں انقلاب کی کوئی جگہ نہیں۔ مرکزیت‘ سیاسی نظم سے زیادہ سماجی بُنت کو حاصل ہو گئی ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہ اصطلاحیں سرمایہ دارانہ کلچرکی دَین ہیں مگر 'اسلامی سوشلزم‘ کی طرح ان کی بھی تعبیرِ نو کی جا سکتی ہے۔
اس کو اپنانے کا ایک بدیہی نتیجہ ہے۔ اب جنگ کی بات نہیں کی جاتی اور خارج میں دشمن تلاش کرنے کے بجائے‘ داخلی اصلاح کو اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اب کسی استعمار کا ذکرہے نہ انقلاب کا۔ یہ فکری ارتقا ان تجربات کا حاصل ہے جو گزشتہ سو برس میں انسان کے دامن میں جمع ہوتے رہے۔ جاپان اور چین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ جاپان نے جنگ کو دیس نکالا دے دیا۔ انقلاب ماؤ کی فکری آغوش میں جوان ہوا مگر آج کے چین میں کوئی انقلاب کی بات نہیں کرتا۔ جنگ‘ انقلاب اور استعمار جیسے الفاظ اب ان کی لغت سے متروک ہو چکے۔ ان ممالک میں استعمار کے خلاف کوئی جلوس برآمد نہیں ہوتا۔ چین میں 'مرگ بر امریکہ‘ کے بینر آویزاں نہیں ہوتے۔ یہ الگ بات کہ اس کے مرگ اور پھر تدفین کی جتنی تیاری چین میں ہو رہی ہے‘ کہیں اور نہیں۔
ہمارا دانشور اس تبدیلی کا ادراک نہیں رکھتا۔ فکرِ معاش اگر ان اصطلاحوں کو اس کی نوکِ زباں پہ لے آئی ہے تو یہ سطحی ہے۔ سول سوسائٹی اس کے لیے محض اُن این جی اوز کا نام ہے جنہیں بیرونِ ملک سے عطیات ملتے ہیں۔ مکالمہ اس کے لیے صرف ایک 'سرگرمی‘ ہے۔ امن محض ایک 'نعرہ‘۔ انسانی حقوق 'میرا جسم میری مرضی‘ کے بینر میں سمٹ آئے ہیں۔ رہے سبز انقلاب کے علمبردار تو وہ اس نظامِ فکر ہی سے بے خبر ہیں جس نے اس نعرے کو جنم دیا۔ غور وفکر اور تجدید واحیا کے تصورات سے‘ وہ مدت ہوئی اعلانِ برأت کر چکے۔ اب ان کی نظری پناہ گاہ روایتی دینی فکر کا وہ آستانہ ہے جہاں سے وہ بارہا دھتکارے گئے اور وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ انہیں بار بار وہیں لے جاتا ہے۔ وہاں سے ان کو کیا مل سکتا ہے؟
شیخِ مکتب کے طریقوں سے کشادِ دل کہاں
کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ
مسلم اصلاحی پیراڈائم سماجی ہے نہ کہ سیاسی۔ اس کی فطری مناسبت اس نظامِ فکر کے ساتھ ہے جو سماجی تعمیر کو اساس بناتا ہے۔ اگر ہم یہ بات شعوری سطح پر قبول کر لیں تو پھر ریاست کے بجائے‘ ہماری اصلاحی کاوشوں کا مرکز معاشرہ اور سماجی اقدار بن جائیں۔ سول سوسائٹی محض این جی اوز کا نام نہیں۔ اس میں مسجد‘ مکتب اور خاندان سمیت تمام سماجی ادارے شامل ہیں۔ ہمیں ان کو مضبوط بنانا ہے۔ سوات کے حادثے کا ہمیں دکھ ہے مگر ان شہدا کو کیا کسی نے سکھایا تھا کہ اس موسم میں دریا کے قریب جانے کے لیے کس طرح کے حفاظتی انتظاما ت ضروری ہیں؟ گوجرانوالہ میں جن میاں بیوی نے دو جواں سال بیٹیوں کو قتل کیا‘ کیا وہ جانتے تھے کہ وہ اس دنیا میں قانون سے بچ نہیں پائیں گے اور دائمی جہنم ان کا ٹھکانا ہے؟
ہمارا دانشور جب ایران کی 'فتح‘ اور 'استعمار کے گماشتوں‘ کی شکست پر خوشی کے شادیانے بجاتا ہے تو فکری افلاس کا یہ منظر اعلان ہے کہ ہم ابھی تک اسی نظامِ فکر کے اسیر ہیں جو سو سال پہلے وجود میں آیا۔ ایران نے یہ جنگ بہادری کے ساتھ لڑی جو اس پر مسلط ہوئی لیکن ایران نے پچھلے چھیالیس برس میں اس جنگ سے بچنے کی کتنی کوشش کی؟ پانچ دہائیوں میں وہاں کس نظامِ فکر کو فروغ دیا گیا؟ اس نے ایران کو مضبوط کیا یا کمزور؟ جاپان اور چین نے اگرحالات سے سیکھا ہے تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ انقلاب کے جس تصور کی ماسکو اور بیجنگ میں تدفین کی جا چکی‘ ہمارے ہاں لوگ اس کی تمثیل کو کیوں اٹھائے پھرتے ہیں؟
تعمیر کا سفر خارج سے نہیں داخل سے شروع ہوگا۔ اس کی خشتِ اوّل خود احتسابی ہے۔ اپنی سماجی قوت کو مجتمع کرنا ہے۔ اس سے ہم کم از کم سوات جیسے حادثوں سے تو بچ جائیں گے۔ ہم نے جس دن جہالت کو زیر کر لیا‘ خارجی دشمن خود ہی زیر نگیں ہو جائیں گے۔