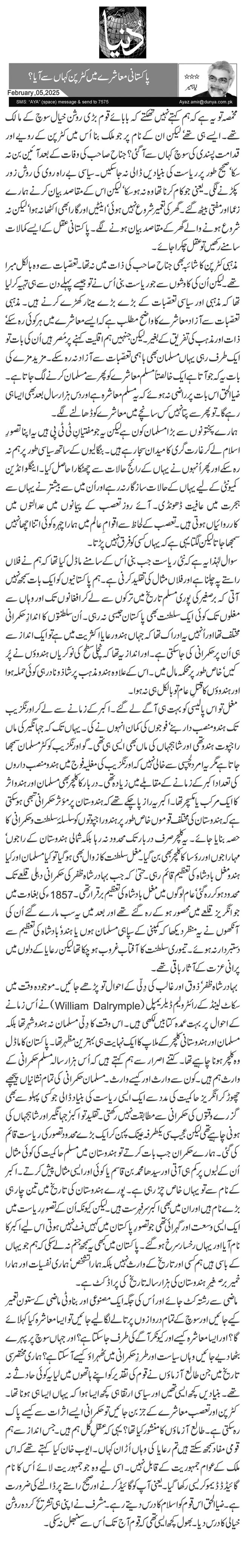پاکستانی معاشرے میں کٹر پن کہاں سے آیا؟
مخمصہ تو یہ ہے کہ ہم کہتے نہیں تھکتے کہ بابائے قوم بڑی روشن خیال سوچ کے مالک تھے۔ ایسے ہی تھے‘ لیکن ان کے نام پر جو ملک بنا اُس میں کٹرپن کے رویے اور قدامت پسندی کی سوچ کہاں سے آ گئی؟ جناح صاحب کی وفات کے بعد آئین بن نہ سکا‘ صحیح طور پر ریاست کی بنیادیں ڈالی نہ جا سکیں۔ سیاسی بے راہ روی کی روش زور پکڑنے لگی۔ یعنی جو کام کرنا تھا وہ نہ ہو سکا‘ لیکن اس کے مقاصد بیان کرنے ہمارے زعما اور مفتی بیٹھ گئے۔ گھر کی تعمیر شروع نہیں ہوئی‘ اینٹیں اور گارا بھی اکٹھا نہ ہوا‘ لیکن نہ شروع ہونے والے گھر کے مقاصد بیان ہونے لگے۔ پاکستانی عقل کے ایسے کمالات سامنے رکھیں تو عقل چکرا جائے۔
مذہبی کٹرپن کا شائبہ بھی جناح صاحب کی ذات میں نہ تھا۔ تعصبات سے وہ بالکل مبرا تھے۔ لیکن اُن کی کاوشوں سے جو ریاست بنی اُس نے تو جیسے پہلے دن سے ہی تہیہ کر لیا تھا کہ مذہبی اور سیاسی تعصبات کے بڑے بڑے مینار کھڑے کرنے ہیں۔ مذہبی تعصبات سے آزاد معاشرے کا واضح مطلب ہے کہ ایسے معاشرے میں ہر کوئی رہ سکے‘ ذات اور مذہب کی تفریق کے بغیر۔ لیکن جنہیں ہم اقلیت کہنے پر مُصر ہیں اُن کی بات تو ایک طرف رہی یہاں مسلمان بھی باہمی تعصبات سے آزاد نہ رہ سکے۔ مزید مزے کی بات یہ کہ جو آتا ہے ایک خالصتاً مسلم معاشرے کو پھر سے مسلمان کرنے لگ جاتا ہے۔ ضیا الحق اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ یہ مسلم معاشرہ ہے اور دس ہزار سال بعد بھی ایسا ہی رہے گا۔ تو پھر سے پتا نہیں کس سانچے میں معاشرے کو ڈھالنے لگے۔
ہمارے پختونوں سے بڑا مسلمان کون ہے لیکن یہ جو مفتیانِ ٹی ٹی پی ہیں یہ اپنا تصورِ اسلام لے کر غارت گری کا میدان سجا رہے ہیں۔ بنگالیوں کے ساتھ سیاسی طور پر ہم نہ رہ سکے اور پھر اُنہوں نے یہاں کے رائج حالات سے چھٹکارا حاصل کیا۔ اینگلو انڈین کمیونٹی کے لیے یہاں کے حالات سازگار نہ رہے اور اُن میں سے بیشتر نے یہاں سے ہجرت میں عافیت ڈھونڈی۔ آئے روز تعصب کے پیمانوں میں عدالتوں میں کارروائیاں ہوتی ہیں۔ تعصب کے لحاظ سے اقوامِ عالم میں ہمارا چہرہ کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن لگتا یہی ہے کہ یہاں کسی کو فرق نہیں پڑتا۔
سوال لہٰذا یہ ہے کہ نئی ریاست جب بنی اُس کے سامنے ماڈل کیا تھا کہ ہم نے فلاں راستے پہ چلنا ہے اور فلاں مثال کی تقلید کرنی ہے۔ ہم پاکستانیوں کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ برصغیر کی پوری مسلم تاریخ میں ترکوں سے لے کر افغانوں تک اور وہاں سے مغلوں تک کوئی ایک سلطنت بھی پاکستان جیسی نہ رہی۔ اُن سلطنتوں کا اندازِ حکمرانی مختلف تھا اور اُنہیں یہ ادراک تھا کہ جہاں ہندو رعایا اکثریت میں ہے تو ایک انداز سے ہی اُن پر حکمرانی کی جا سکتی ہے۔ اور انداز یہ تھا کہ نچلی سطح کی نوکریاں ہندوؤں نے پُر کیں‘ خاص طور پر محکمہ مال میں۔ اس کے علاوہ ہندو مذہب پر شاذو نادر ہی کوئی حملہ ہوا اور ہندوؤں کا قتلِ عام تو بالکل ہی نہ ہوا۔
مغل تو اس پالیسی کو بہت ہی آگے لے گئے۔ اکبر کے زمانے سے لے کر اورنگزیب تک ہندو منصب دار بنے‘ فوجوں کی کمان انہوں نے کی۔ یہاں تک کہ جہانگیر کی ماں راجپوت ہندو تھی اور شاہجہاں کی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ گو اورنگزیب کو کٹر مسلمان سمجھا جاتا ہے مگر یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ اورنگزیب کی مغلیہ فوج میں ہندو منصب داروں کی تعداد اکبر کے زمانے کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ دربار کا کلچر بھی مسلمان اور ہندو اثر کا ایک مرکب یا مکسچر تھا۔ اکبر یہ راز پا چکے تھے کہ ہندوستان پر مؤثر حکمرانی تبھی ہو سکتی ہے کہ ہندوستان کی مختلف قوموں خاص طور پر ہندو راجپوتوں کو سلسلۂ سلطنت وحکمرانی کا حصہ بنایا جائے۔ یہ کلچر صرف دربار تک محدود نہ رہا بلکہ شمالی ہندوستان کے راجوں‘ مہاراجوں اور رؤسا کا کلچر بھی بن گیا۔ مغل سلطنت کا زوال بھی ہو گیا تو کیا مسلمان اور کیا ہندو مغل بادشاہ کی تعظیم قائم رہی۔ حتیٰ کہ جب بہادر شاہ ظفر کی حکمرانی دہلی قلعے تک محدود ہو کر رہ گئی‘ عام لوگوں میں مغل بادشاہ کی تعظیم برقرار تھی۔ 1857ء کی بغاوت میں جو انگریز قلعے میں محصور ہو کے رہ گئے تھے اور بعد میں یہ سب مارے گئے اُن کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ کمپنی کے سپاہی مسلمان ہوں یا ہندو‘ بادشاہ کی تعظیم سے دستبردار نہ ہوئے۔ تیموری سلطنت کا آفتاب غروب ہو چکا تھا لیکن رعایا کے دلوں میں پرانی عزت کے آثار باقی تھے۔
بہادر شاہ ظفر‘ ذوق اور غالب کی دِلّی کے احوال تو پڑھے جائیں۔ موجودہ وقت میں سکاٹ لینڈ کے رائٹر ولیم ڈیلریمپل (William Dalrymple) نے اُس زمانے کے احوال پر بہت عمدہ کتابیں لکھی ہیں۔ اس وقت کا دِلّی مسلمان نہ ہندو شہر تھا بلکہ مسلمان اور ہندوستانی کلچر کے ملاپ کا ایک نہایت ہی بہترین مظہر تھا۔ پاکستان کا ماڈل وہ کلچر ہونا چاہیے تھا۔ کتنے اصرار سے ہم کہتے ہیں کہ اُس ہزار سالہ مسلم حکمرانی کے وارث ہم ہیں۔ کون سے وارث اور کیسے وارث۔ مسلمان حکمرانی کی تمام نشانیاں پیچھے چھوڑ کر انگریز حاکمیت کی مدد سے ایک ایسی ریاست کی بنیاد ڈالی جو کسی پہلو سے بھی گزرے وقتوں کی حکمرانی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تقلید تو اکبر‘ جہانگیر اور شاہجہاں کی ہونی چاہیے تھی لیکن عجیب سی یکطرفہ عینک پہن کر ایک بڑے محدود تصور کی ریاست قائم کی گئی۔ ہمارے حکمران جب بات کرتے تو ہندوستان میں مسلم حاکمیت کی کوئی مثال اُن کے لبوں پر کم ہی آتی اور سیدھا محمد بن قاسم یا کوئی اور ایسی مثال پیش کرتے۔ اکبر کے نام سے تو یہاں خاص چڑ رہی ہے۔ پورے ہندوستان کی تاریخ میں تین چار ہی بڑے نام ہیں اور ان میں بھی اکبر سرفہرست ہیں۔ لیکن کیونکہ اُن کے تصورِ ریاست میں ایک ایسی وسعت اور گہرائی تھی جو تصورِ پاکستان میں کہیں فٹ نہیں ہوتی اس لیے اکبر کا نام آیا اور یہاں رخسار سرخ ہو گئے۔ پاکستان میںکبھی یہ سمجھ جنم نہ لے سکی کہ ہم جو یہاں کے باسی ہیں ہم کسی اور تاریخ کے وارث نہیں بلکہ ہمارا تشخص‘ ہماری نفسیات اور ہمارا خمیر برصغیرِ ہندوستان کی ہزار سالہ تاریخ کی پراڈکٹ ہے۔
ماضی سے رشتہ کٹ جائے اور اُس کی جگہ ایک مصنوعی اور بناوٹی ماضی کے ستون تعمیر کیے جائیں اور سوچ کے تمام دروازوں پر تالے لگا لیے جائیں تو ایسا معاشرہ کیا کہلائے گا؟ اور ایسا معاشرہ کیسے اور کیونکر آگے کی طرف جا سکتا ہے؟ اور جہاں سوچ پر پہرے بٹھا دیے جائیں وہاں سیاست اور طرزِ حکمرانی میں ٹھہراؤ کیسے آ سکتا ہے؟ ہماری مختصر سی تاریخ میں جن طالع آزماؤں نے قوم کی تقدیر کو اپنے ہاتھوں میں لیا یہ کوئی حادثے نہ تھے۔ بنیادیں کچھ ایسی تھیں اور سیاسی ارتقا ہی کچھ ایسا ہوا کہ یہاں ایسا ہی ہونا تھا۔ کٹرپن اور تعصب معاشرے کے جز بن جائیں تو حکمرانی ایسے اثرات سے کیسے پاک رہ سکتی ہے۔ طالع آزماؤں کا منشور کیا تھا؟ یہی کہ عقلِ کُل ہم ہیں۔ جس انداز سے ہم قومی مفاد سمجھ سکتے ہیں تم رعایا کی وہاں اُڑان کہاں۔ ایوب خان کیا کہتے تھے کہ اس ملک کے عوام جمہوریت کے قابل نہیں۔ اسی لیے وہ جو جمہوریت لائے اُس کا نام گائیڈڈ ڈیموکریسی رکھا گیا۔ یعنی آپ کو گائیڈ کرنے اور صحیح راستے پر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ضیا الحق اس قوم کو اسلام کا درس دیتے رہے۔ مشرف نے اپنی ہی تشریح کردہ روشن خیالی کا درس دیا۔ بھول کچھ ایسی تھی کہ قوم آج تک اُس سے سنبھل نہ سکی۔