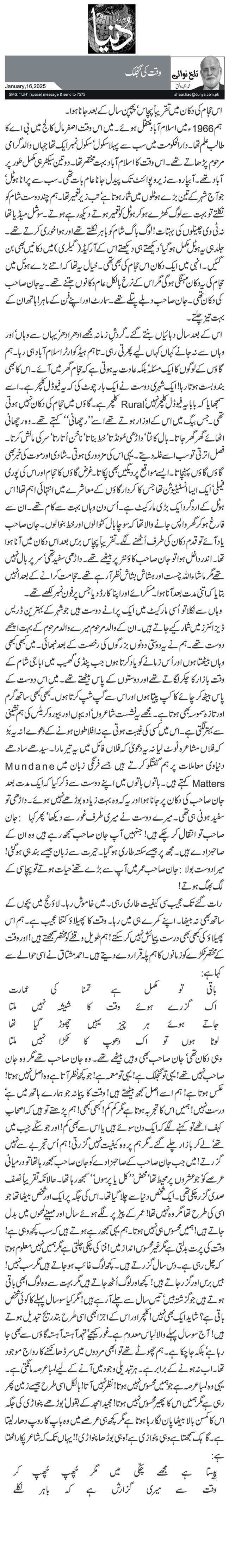وقت کی گنجلک
اس حجام کی دکان میں تقریباً پچاس‘ پچپن سال کے بعد جانا ہوا۔
ہم 1966ء میں اسلام آباد منتقل ہوئے۔ میں اس وقت اصغر مال کالج میں بی اے کا طالب علم تھا۔ دارالحکومت میں سب سے پہلا سکول‘ سکول نمبر ایک تھا جہاں والد گرامی مرحوم پڑھاتے تھے۔ اس وقت کا اسلام آباد بہت مختصر تھا۔ دو تین سیکٹر ہی مکمل طور پر آباد تھے۔ آبپارہ سے زیرو پوائنٹ تک پیدل جانا عام بات تھی۔ سب سے پرانا ہوٹل‘ جو آج شہر کے تین بڑے ہوٹلوں میں شمار ہوتا ہے‘ تب زیر تعمیر تھا۔ ہم چند دوست شام کو نکلتے تو بہت سے لوگ کھڑے ہو کر ہوٹل کو تعمیر ہوتے دیکھ رہے ہوتے۔ سوشل میڈیا تھا نہ ٹی وی چینلوں کی بہتات! لوگ باگ شام کو باہر نکلتے تھے اور ہوا خوری کرتے تھے۔ جلد ہی یہ ہوٹل مکمل ہو گیا‘ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے آرکیڈ (گیلری) میں دکانیں بھی بن گئیں۔ انہی میں ایک دکان اس حجام کی بھی تھی۔ خیال یہ تھا کہ اتنے بڑے ہوٹل میں حجام کی یہ دکان مہنگی ہو گی مگر اس کے نرخ بالکل عام دکانوں جتنے تھے۔ یہ جان صاحب کی دکان تھی۔ جان صاحب دبلے پتلے تھے۔ سمارٹ اور اپنے فن کے ماہر! ہاتھ ان کے بہت تیز چلتے۔
اس کے بعد سال دہائیاں بنتے گئے۔ گردشِ زمانہ مجھے ادھر ادھر‘ یہاں سے وہاں‘ اور وہاں سے نہ جانے کہاں کہاں لیے پھرتی رہی۔ تاہم ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ہی رہا۔ ہم گاؤں کے لوگوں کا ایک مسئلہ‘ بلکہ عادت یہ ہوتی ہے کہ حجام گھر میں آئے۔ اس کا بھی بندوبست ہوتا رہا! ایک شہری دوست نے ایک بار چوٹ کی کہ یہ فیوڈل کلچر ہے۔ اسے سمجھایا کہ بابا یہ فیوڈل کلچر نہیں‘ Rural کلچر ہے۔ گاؤں میں حجام کی دکان نہیں ہوتی تھی۔ جس بیگ میں اس کے اوزار ہوتے تھے اسے ''رچھانی‘‘ کہتے تھے۔ وہ رچھانی اٹھائے گھر گھر جاتا۔ بال کاٹتا‘ داڑھی مُونڈتا‘ خط بناتا‘ ناخن اُتارتا‘ سر کی مالش کرتا۔ فصل اترتی تو سب اسے غلہ دیتے۔ یہی اس کی مزدوری ہوتی۔ شادی اور موت کی خبر بھی گاؤں گاؤں پہنچاتا۔ ایسے مواقع پر دیگیں بھی پکاتا۔ غرض گاؤں کا حجام اور اس کی پوری فیملی‘ ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جس کا کردار گاؤں کے معاشرے میں انتہائی اہم تھا! اس ہوٹل کے اردگرد ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ اُس دن وہاں بہت سے کام تھے۔ ان سے فارغ ہو کر گھر واپس جانے والا تھا کہ سوچا بال کٹوا لوں اور خط بنوا لوں۔ جان صاحب یاد آئے تو قدم دکان کی طرف اُٹھنے لگے۔ تقریباً پچاس برس بعد اس دکان میں آنا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا تو جان صاحب کاؤنٹر پر بیٹھے تھے۔ داڑھی سفید تھی‘ سر پر بال نہیں تھے مگر ماشاء اللہ چست اور ہشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ حجامت کرانے کے بعد انہیں بتایا کہ اتنی مدت بعد آنا ہوا۔ مسکرائے اور اپنا کارڈ دیا جس پر فون نمبر لکھے تھے۔
وہاں سے نکلا تو اُسی مارکیٹ میں ایک پرانے دوست ہیں جو شہر کے بہترین ڈریس ڈیزائنرز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے والد مرحوم میرے والد مرحوم کے بہت اچھے دوست تھے۔ ہم نے یہ دوستی دونوں بزرگوں کی رخصت کے بعد نبھائی۔ میں کبھی کبھی وہاں بیٹھتا ہوں اور اُس زمانے کو یاد کرتا ہوں جب پنڈی گھیب میں ابا جی شام کے وقت بازار کا چکر لگاتے تھے اور دوستوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ میں اس دوست کے پاس بیٹھ کر چائے کا کپ پیتا ہوں اور اس سے گپ شپ کرتا ہوں۔ کبھی کبھی ساتھ گرم اور تازہ سموسہ بھی ہوتا ہے۔ مجھے یہ نشست شاعروں‘ ادیبوں اور بیورو کریٹس کی ہم نشینی سے بہتر لگتی ہے۔ اس میں کسی کی غیبت ہوتی ہے نہ افلاطون ہونے کے دعوے! نہ یہ بَڑ کہ فلاں مشاعرہ لُوٹ لیا نہ یہ دعویٰ کہ فلاں فائل میں یہ تیر مارا۔ سیدھے سادھے دنیاوی معاملات پر ہم گفتگو کرتے ہیں جسے فرنگی زبان میں Mundane Matters کہتے ہیں۔ باتوں باتوں میں اپنے دوست سے ذکر کیا کہ ایک مدت بعد جان صاحب کی دکان پر جانا ہوا اور یہ کہ وہ بہت زیادہ بوڑھے نہیں ہوئے۔ داڑھی تو سفید ہونی ہی تھی۔ میرے دوست نے میری طرف غور سے دیکھا‘ پھر کہا: جان صاحب تو انتقال کر چکے ہیں! جنہیں آپ جان صاحب سمجھ رہے ہیں وہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ حیرت سے زبان جیسے بند ہی ہو گئی! میرا دوست بولا: جان صاحب عمر میں آپ سے بڑے تھے‘ حیات ہوتے تو پچاسی کے لگ بھگ ہوتے!
رات گئے تک عجیب سی کیفیت طاری رہی۔ میں خاموش رہا۔ لاؤنج میں بچوں کے ساتھ بھی نہ بیٹھا۔ اپنے کمرے ہی میں رہا۔ وقت کا پھیلاؤ کتنا عجیب ہے۔ ہم اس پھیلاؤ کی کبھی بھی درست پیمائش نہیں کر سکتے! ہم طویل وقفے کو مختصر سمجھتے ہیں! اور وقت کے مختصر ٹکڑے کو زمانوں کاہم پلہ قرار دے دیتے ہیں۔ احمد مشتاق نے اسی حوالے سے کہا ہے:
باقی تو مکمل ہے تمنا کی عمارت
اک گزرے ہوئے وقت کا شیشہ نہیں ملتا
جاتے ہوئے ہر چیز یہیں چھوڑ گیا تھا
لوٹا ہوں تو اک دھوپ کا ٹکڑا نہیں ملتا
وہی دکان تھی‘ جان صاحب بھی وہیں بیٹھے تھے۔ وہ جان صاحب تھے مگر وہ جان صاحب نہیں تھے! یہی تو گنجلک ہے! یہی تو معمہ ہے! جو کچھ نظر آتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا! عکس ہوتا ہے! ہم اسے اصل سمجھ بیٹھتے ہیں! وقت کا پیمانہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے‘ درست نہیں! ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے مگر کم کم! کبھی کبھی! ہم پڑھتے تو ہیں کہ اصحابِ کہف اٹھے تو کہنے لگے کہ ایک دن سوئے ہیں یا اس سے بھی کم! اور جو سکّے جیب میں تھے‘ لے کر بازار چلے گئے۔ مگر ہم پر وہ کیفیت نہیں گزرتی! ہم اُس تجربے سے نہیں گزرتے! میں جب جان صاحب کے صاحبزادے کو جان صاحب سمجھ رہا تھا تو درمیانی عرصے کو‘ جو عشروں پر محیط تھا‘ محض ''کل یا پرسوں‘‘ سمجھ رہا تھا۔ حالانکہ تقریباً نصف صدی گزر چکی تھی۔ ایک شخص دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کی جگہ پر ایک اور شخص بیٹھا تھا جو اسی کی طرح تھا مگر وہ نہیں تھا! عمر کے پیڑ پر لگے ہوئے سال اور مہینے لمحوں میں بدل جاتے ہیں! ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ وہی ہے! وقت کی پرت بدلتی ہے مگر غیر محسوس انداز میں! فنا کی چکی چلتی ہے مگر ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ چل رہی ہے۔ دس سال گزرتے ہیں۔ کچھ لوگ غائب ہو جاتے ہیں مگر سب نہیں! بیس برس اور گزر جاتے ہیں! کچھ اور لوگ اُٹھ جاتے ہیں مگر بہت سے وہ لوگ ابھی باقی ہوتے ہیں جو گزشتہ بیس‘ تیس سال سے چلے آ رہے ہیں! مگر کیا سو سال پہلے کا کوئی شخص باقی ہے؟ شاید ایک بھی نہیں! کلچر اور اس کے اجزا بھی اسی طرح بتدریج تبدیل ہوتے ہیں! آج سو سال پہلے والا لباس معدوم ہے۔ غور کیجیے‘ تہمد آہستہ آہستہ گاؤں سے بھی جا رہا ہے‘ بلکہ جا چکا ہے۔ ہم چھوٹے تھے تو ابھی مردوں میں سر ڈھانکنے کا رواج موجود تھا۔ اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر تبدیلی وجود میں آنے کے لیے لمبا عرصہ مانگتی ہے۔ یہی وہ لمبا عرصہ ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا! نظر نہیں آتا! بالکل اسی طرح جیسے زمین پھر رہی ہے مگر ہمیں اس کا پھیر محسوس نہیں ہوتا! مجید امجد کے بقول‘ بوڑھے پنواڑی کی جگہ اس کا کمسن بالا بیٹھا پان لگا رہا ہوتا ہے مگر کچھ ہی عرصے میں وہ باپ کا روپ دھار لیتا ہے۔ گاہک سمجھتا ہے وہی پنواڑی ہے! وہی بوڑھا پنواڑی!! یہاں تک کہ شاعر پکار اٹھتا ہے:
پِیستا ہے مجھے چکّی میں مگر چُھپ چُھپ کر
وقت سے میری گزارش ہے کہ باہر نکلے