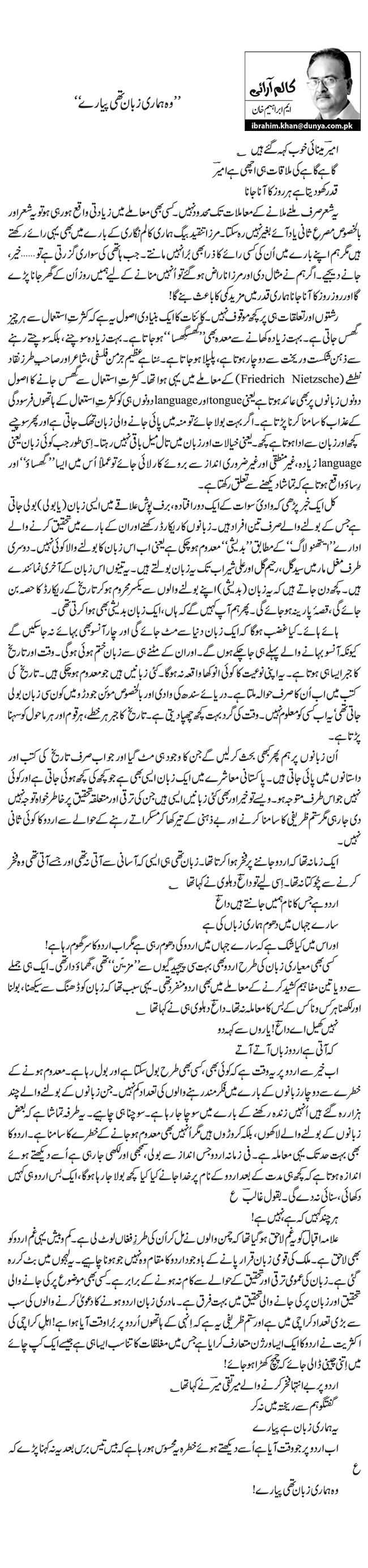تاریخ اشاعت 2018-02-24
’’وہ ہماری زبان تھی پیارے‘‘
امیرؔ مینائی خوب کہہ گئے ہیں ؎
گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے امیرؔ
قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا
یہ شعر صرف ملنے ملانے کے معاملات تک محدود نہیں۔ کسی بھی معاملے میں زیادتی واقع ہو رہی ہو تو یہ شعر اور بالخصوص مصرعِ ثانی یاد آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مرزا تنقید بیگ ہماری کالم نگاری کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتے ہیں مگر ہم اپنے بارے میں اُن کی کسی رائے کا ذرا بھی بُرا نہیں مانتے۔ جب ہاتھی کی سواری گزرتی ہے تو ... خیر، جانے دیجیے۔ اگر ہم نے مثال دی اور مرزا ناراض ہو گئے تو اُنہیں منانے کے لیے ہمیں روز اُن کے گھر جانا پڑے گا اور روز روز کا آنا جانا ہماری قدر میں مزید کمی کا باعث بنے گا!
رشتوں اور تعلقات ہی پر کچھ موقوف نہیں۔ کائنات کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کثرتِ استعمال سے ہر چیز گِھس جاتی ہے۔ بہت زیادہ کھانے سے معدہ بھی ''گِھسگِھسا‘‘ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ سوچنے، بلکہ سوچتے رہنے سے ذہن شکست و ریخت سے دوچار ہوتا ہے، پلپلا ہو جاتا ہے۔ سُنا ہے عظیم جرمن فلسفی، شاعر اور صاحبِ طرز نقاد نطشے (Friedrich Nietzsche) کے معاملے میں یہی ہوا تھا۔ کثرتِ استعمال سے گِھس جانے کا اصول دونوں زبانوں پر بھی عائد ہوتا ہے یعنی tongue اور language دونوں ہی کو کثرتِ استعمال کے ہاتھوں فرسودگی کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر بہت بولا جائے تو منہ میں پائی جانے والی زبان تھک جاتی ہے اور پھر سوچیے کچھ اور زبان سے ادا ہوتا ہے کچھ۔ یعنی خیالات اور زبان میں تال میل باقی نہیں رہتا۔ اِسی طور جب کوئی زبان یعنی language زیادہ، غیر منطقی اور غیر ضروری انداز سے بروئے کار لائی جائے تو عملاً اُس میں ایسا ''گِھساؤ‘‘ اور رِساؤ واقع ہوتا ہے کہ تماشا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
کل ایک خبر پڑھی کہ وادیٔ سوات کے ایک دور افتادہ، برف پوش علاقے میں ایسی زبان (یا بولی) بولی جاتی ہے جس کے بولنے والے صرف تین افراد ہیں۔ زبانوں کا ریکارڈ رکھنے اور ان کے بارے میں تحقیق کرنے والے ادارے ''ایتھنو لاگ‘‘ کے مطابق ''بدیشی‘‘ معدوم ہو چکی ہے یعنی اب اس زبان کا بولنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف مغل مار میں سید گل، رحیم گل اور علی شیر اب تک یہ زبان بولتے ہیں۔ یہ تینوں اس زبان کے آخری نمائندے ہیں۔ کچھ دن جاتے ہیں کہ یہ زبان (بدیشی) اپنے بولنے والوں سے یکسر محروم ہو کر تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی، قصۂ پارینہ ہو جائے گی۔ پھر ہم آپ کہیں گے کہ ہاں، ایک زبان بدیشی بھی ہوا کرتی تھی۔
ہائے ہائے۔ کیا غضب ہوگا کہ ایک زبان دنیا سے مٹ جائے گی اور چار آنسو بھی بہائے نہ جا سکیں گے کیونکہ آنسو بہانے والے پہلے ہی جا چکے ہوں گے۔ اور ان کے مٹنے ہی سے زبان ختم ہوئی ہو گی۔ وقت اور تاریخ کا جبر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا کوئی انوکھا واقعہ نہ ہوگا۔ کئی زبانیں ہیں جو معدوم ہوچکی ہیں۔ تاریخ کی کتب میں اب اُن کا صرف حوالہ ملتا ہے۔ دریائے سندھ کی وادی اور بالخصوص موئن جو دڑو میں کون سی زبان بولی جاتی تھی‘ یہ اب کسی کو معلوم نہیں۔ وقت کی گرد بہت کچھ چھپا دیتی ہے۔ تاریخ کا جبر ہر خطے، ہر قوم اور ہر ماحول کو سہنا پڑتا ہے۔
اُن زبانوں پر ہم پھر کبھی بحث کر لیں گے جن کا وجود ہی مٹ گیا اور جو اب صرف تاریخ کی کتب اور داستانوں میں پائی جاتی ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں ایک زبان ایسی بھی ہے جو کچھ کی کچھ ہوئی جاتی ہے اور کوئی نہیں جو اس طرف متوجہ ہو۔ ویسے تو خیر اور بھی کئی زبانیں ایسی ہیں جن کی ترقی اور متعلقہ تحقیق پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی مگر ستم ظریفی کا سامنا کرنے اور بے ذہنی کے تیر کھاکر مسکراتے رہنے کے حوالے سے اردو کا کوئی ثانی نہیں۔
ایک زمانہ تھا کہ اردو جاننے پر فخر ہوا کرتا تھا۔ زبان تھی ہی ایسی کہ آسانی سے آتی نہ تھی اور جسے آتی تھی وہ فخر کرنے سے چُوکتا نہ تھا۔ اِسی لیے تو داغؔ دہلوی نے کہا تھا ؎
اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغؔ
سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے
اور اس میں کیا شک ہے کہ سارے جہاں میں اردو کی دھوم رہی ہے مگر اب اردو کا سر گھوم رہا ہے!
کسی بھی معیاری زبان کی طرح اردو بھی بہت سی پیچیدگیوں سے ''مزیّن‘‘ تھی، گھماؤ دار تھی۔ ایک ہی جملے سے دو یا تین مفاہیم کشید کرنے کے معاملے میں بھی اردو منفرد تھی۔ یہی سبب تھا کہ زبان کو ڈھنگ سے سیکھنا، بولنا اور لکھنا ہر کس و ناکس کے بس کا معاملہ نہ تھا۔ داغؔ دہلوی ہی نے کہا تھا ؎
نہیں کھیل اے داغؔ! یاروں سے کہہ دو
کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے
اب خیر سے اردو پر یہ وقت ہے کہ کوئی بھی، کسی بھی طرح بول سکتا ہے اور بول رہا ہے۔ معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار زبانوں کے بارے میں فکر مند رہنے والوں کی تعداد کم نہیں۔ جن زبانوں کے بولنے والے چند ہزار رہ گئے ہیں اُنہیں زندہ رکھنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ سوچنا ہی چاہیے۔ یہ طرفہ تماشا ہے کہ بعض زبانوں کے بولنے والے لاکھوں، بلکہ کروڑوں ہیں مگر اُنہیں بھی معدوم ہو جانے کے خطرے کا سامنا ہے۔ اردو کا بھی بہت حد تک یہی معاملہ ہے۔ فی زمانہ اردو جس انداز سے بولی، سمجھی اور لکھی جا رہی ہے اُسے دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ہی مدت کے بعد اردو کے نام پر خدا جانے کیا کیا کچھ بولا جا رہا ہو گا، ایک بس اردو ہی کہیں دکھائی، سنائی نہ دے گی۔ بقول غالبؔ ع
ہرچند کہیں کہ ہے، نہیں ہے!
علامہ اقبالؔ کو یہ غم لاحق ہوگیا تھا کہ چمن والوں نے مل کر اُن کی طرزِ فغاں لوٹ لی ہے۔ کم و بیش یہی غم اردو کو بھی لاحق ہے۔ ملک کی قومی زبان قرار پانے کے باوجود اردو کا مقام وہ نہیں جو ہونا چاہیے۔ یہ لہجوں میں بٹ کر رہ گئی ہے۔ زبان کی عمومی ترقی اور تحقیق کے حوالے سے کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی بھی موضوع پر کی جانے والی تحقیق اور زبان پر کی جانے والی تحقیق میں بہت فرق ہے۔ مادری زبان اردو ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد کراچی میں ہے اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اِنہی کے ہاتھوں اُردو پر بُرا وقت آیا ہوا ہے! اہلِ کراچی کی اکثریت نے اردو کا ایک ایسا ورژن متعارف کرایا ہے جس میں مغلظات کا تناسب ایسا ہی ہے جیسے ایک کپ چائے میں اِتنی چینی ڈالی جائے کہ چمچ کھڑا ہو جائے!
اردو پر بے انتہا فخر کرنے والے میر تقی میرؔ نے کہا تھا ؎
گفتگو ہم سے ریختہ میں نہ کر
یہ ہماری زبان ہے پیارے
اب اردو پر جو وقت آیا ہے اُسے دیکھتے ہوئے خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بیس تیس برس بعد یہ نہ کہنا پڑے کہ ع
وہ ہماری زبان تھی پیارے!
ایم ابراہیم خان کے مزید کالمز
’’سرنگوں‘‘ سے تو گزرنا ہی پڑے گا 2024-01-30 تکون 2024-01-29 صرف چین پریشان نہیں 2024-01-28 مل کر ہی چلنا پڑے گا 2024-01-27 ماحول کافی نہیں ہوتا 2024-01-26 ہم خواب کدے میں جی رہے ہیں 2024-01-25 مصنوعی ذہانت‘ غیر مصنوعی چیلنج 2024-01-24 ڈپریشن کیفیت ہے‘ بیماری نہیں 2024-01-23 مینوفیکچرنگ کی جنگ 2024-01-22 مشکلات تو وہاں بھی ہیں 2024-01-21