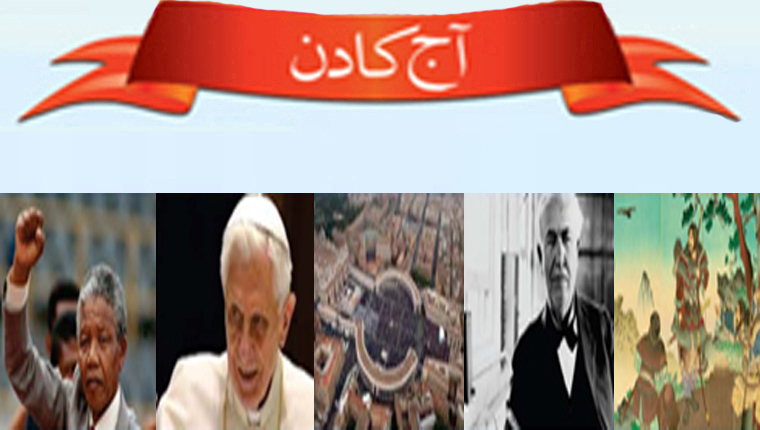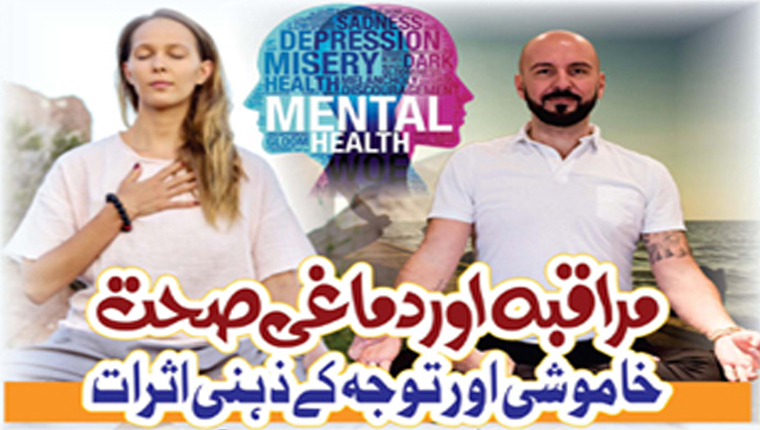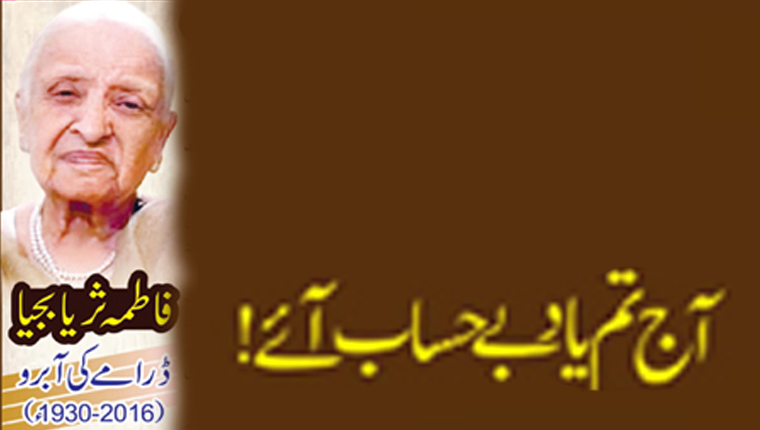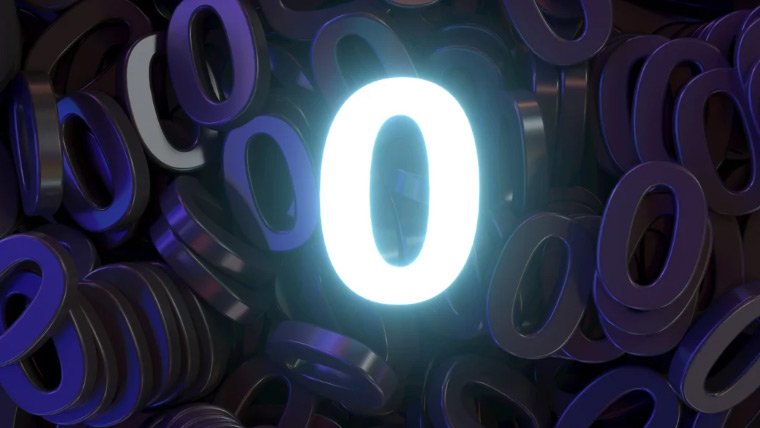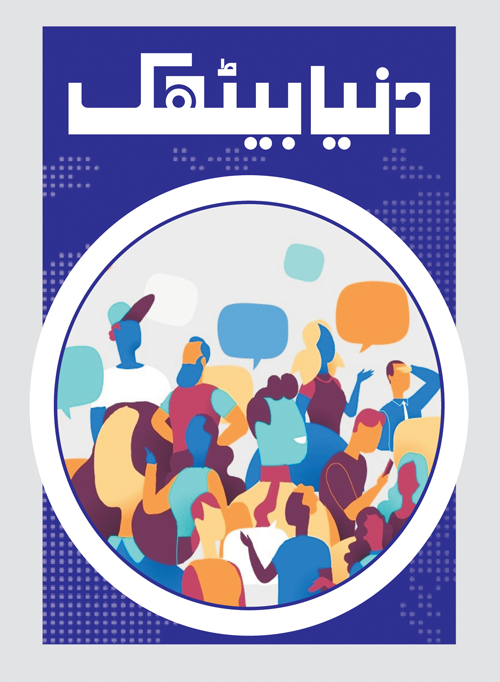ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی
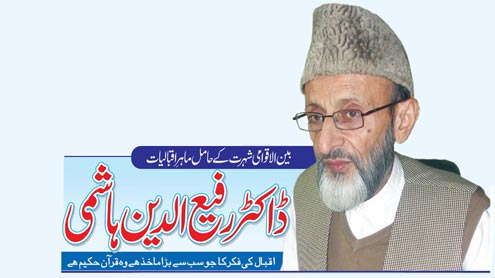
اسپیشل فیچر
ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اپنی علمی و ادبی استعداد‘ تدریسی‘ تحقیقی اور تنقیدی مقام و مرتبہ اور اقبال شناسی کے حوالے سے ملکی ہی نہیں بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ انھوں نے تقریباً۵۳ برس کالجوں اورپنجاب یونی ورسٹی میں درس وتدریس کے فرائض انجام دیے۔اس کے ساتھ ساتھ وہ علمی واد بی تحقیق میں بھی مصروف رہے۔ بیرونی ممالک میں اقبال پر کانفرنسوں میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی۔ آپ دائتوبنکایونیورسٹی ٹوکیو جاپان میں فروری مارچ 2002ء میں وزیٹنگ سکالر رہے۔ ایچ ای سی ایمی نینٹ پروفیسر کے طور پرشعبہ اقبالیات پنجاب یونیورسٹی لاہور سے منسلک رہے۔ علاوہ ازیں وہ طویل عرصے تک اقبال اکادمی پاکستان سے وابستہ چلے آرہے ہیں۔آپ اقبال اکادمی کے تاحیات رکن اوراس کی گورننگ باڈی اورایگزیکٹوباڈی کے بھی رکن ہیں۔اس کے علمی رسالے’’اقبالیات‘‘کی بلکہ بہت سے دوسرے علمی وتحقیقی مجلوں کی ادارتی اورمشاورتی مجالس میں بھی شامل ہیں۔اس کے علاوہ آپ ادبی کمیٹی بزم اقبال لاہور کے بھی رکن ہیں۔اسی طرح آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ اردواورشعبہ اقبالیات اور بورڈ آف ایڈوانس سٹڈیزاینڈ ریسرچ کے ساتھ کئی طرح سے منسلک رہے ہیں۔ آپ کو علمی و ادبی اور تحقیقی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات کا حق دار قرار دیا گیا جن میںداؤدادبی ایوارڈ1982ء،بیسٹ یونی ورسٹی ٹیچرزایوارڈ2000ء اورقومی صدارتی اقبال ایوارڈ 2005ء اہم ہیں۔ آپ کی چالیس سے اوپرتصنیفات اردوزبان وادب کے حوالے سے تحقیقی وعلمی سطح پر بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کے ساتھ ملاقات کا موقع میسر آیا جس کا احوال معزز قارئین کے ذوقِ مطالعہ کی نذر ہے۔س:آپ یونیورسٹی میں آپ اوّل آئے؟ج:جی ہاں،اوّل آیااوراس بناپریونیورسٹی گولڈمیڈل ملا۔اسی طرح انجمن ترقیٔ اردو پاکستان کی طرف سے’’ تمغائے بابائے اردو‘‘بھی ملا۔س:اچھاڈاکٹرصاحب،لکھناکب شروع کیا؟ج: لکھنے لکھانے کاسلسلہ سکول کے زمانے سے شروع ہوا۔ ایف اے کے زمانے میں کچھ افسانے اورانشایے لکھے اور کچھ طنزومزاح بھی۔لیکن جب ایم اے میں پہنچا تو میری توجہ تحقیق اور تنقید کی طرف زیادہ ہوگئی۔ لیکن تخلیق سے بھی تعلق برقراررہااور ابھی تک یہ تعلق قائم ہے۔ دو سفر نامے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک اندلس کا ’’پوشیدہ تری خاک میں‘‘ اور دوسرا جاپان کا ’’سورج کو ذرا دیکھ‘‘ اس کے علاوہ بھارت ،برطانیہ اورشمالی علاقہ جات کے اسفارکی رودادیں بھی لکھی ہیں کچھ مزیدسفرنامے لکھنا چاہتاہوں مگرتحقیقی مشاغل مہلت نہیں دیتے۔س:اچھا،کچھ عملی زندگی کے بارے میں بھی…ج:عملی زندگی ،اس میں صحافت میں جانے کے خاصے مواقع تھے مگرمزاجی مناسبت مجھے درس وتدریس سے تھی،اس لیے سوچا کہ پڑھنا پڑھانا بہتررہے گا۔شروع میں مجبوراً کچھ عرصہ اخبار، رسالوں میں کام کیاپھرجونہی موقع ملا،تدریس میں آگیا۔ غزالی کالج جھنگ صدر‘ ایف سی کالج لاہور‘ میونسپل کالج چشتیاں‘ انبالہ مسلم کالج سرگودھامیں پڑھاتا رہا پھر جب گورنمنٹ سروس میں آگیا تو گورنمنٹ کالج مری‘ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا۔ یہاں سے میں 1982ء میں پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے شعبہ اردو میں آگیا اور 2002ء میں یہیں سے ریٹائر ہوا۔ مزیددو برس پڑھایا لیکن اب مصروفیت لکھنے پڑھنے اور تحقیق و تصنیف ہی کی ہے۔ویسے یونی ورسٹی سے تعلق کئی طرح کااب بھی قائم ہے۔دائرہ معارف اقبال کے لیے ان دنوں کچھ مقالات زیرتحریرہیں۔س: اقبالیات آپ کا مرغوب موضوع رہا۔ تخصیص کے ساتھ اس سے وابستگی اور اسی میں تحقیق کے کیا محرکات تھے؟ج: ایک تو یہ تھا کہ ایم اے اردو کے نصاب میں علامہ اقبال کے مطالعے کا ایک پورا پرچہ ہے جس میں ان کی شاعری اور ان کے افکار کا تفصیلی مطالعہ ہوتا ہے۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کا اعزاز ہے کہ اس کے ایم اے اردواورفارسی کے نصاب میںاقبالیات کا پورا پرچہ شامل ہے۔توایک وابستگی تویہ تھی۔ دوسرے اس سے پہلے میرے گھر کا ماحول اور خاندانی پس منظر بھی اقبال کی جانب رغبت دلانے کے لیے سازگار تھا۔ میں جب پانچویں یا چھٹی جماعت میں تھا‘ ہمارے گھر میں بانگِ درا کا ایک نسخہ ہوتا تھا۔ میں اس کو کبھی کبھی دیکھتا تھا۔ اس میں شروع کی بعض نظمیں مثلاً’’پرندے کی فریاد‘‘یا’’ایک مکڑا ور مکھی‘‘یا’’ہمدردی‘‘وغیرہ دلچسپ محسوس ہوتی تھیں تویہ چیز اقبال سے ابتدائی دلچسپی کا سبب بنی۔ پھر ایف اے کے زمانے میں’’بالِ جبریل‘‘ میرے ہاتھ لگی۔ چھٹیوں کا زمانہ تھا، بار بار پڑھنے سے بہت سا حصہ مجھے یا دہوگیا ۔جب ایم اے میں اقبال کوپڑھا تو سب پچھلی باتیں تازہ ہوگئیں اور اس طرح وہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کیا جس کے لیے میرے مقالے کا موضوع تھا ’’تصانیف اقبال کا تحقیقی اور توضیحی مطالعہ‘‘ وہ مقالہ تین مرتبہ چھپا ہے۔یوںزیادہ تر میری توجہ اقبال پر ہی رہی ہے۔ اقبالیات پرمیری چھوٹی بڑی بیس کتابیں ہیں۔ مثلاً’’ اقبال کی طویل نظمیں‘‘ میری سب سے پہلی کتاب ہے۔ وہ 1974ء میں چھپی تھی اب تک اس کے سات آٹھ ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ س: ڈاکٹر صاحب! آپ نے پی ایچ ڈی کے لیے ’’تصانیف اقبال کا تحقیقی اور توضیحی مطالعہ‘‘ کا موضوع منتخب کیا۔ اس میں اقبال کی تمام کتب اور ان میں شامل نظمیں‘ غزلیں‘ قطعات‘ رباعیات اور فردیات سب کچھ آ جاتا ہے، ان سب کا احاطہ کرنا آپ کے لیے کس قدر مشکل رہا۔ ج: اس میں جو تحقیقی مطالعہ تھا وہ اس طرح تھا کہ اقبال نے اپنی شاعری اور نثر کو کیسے جمع کیا اور کب اور کیسے شائع کیا مثلاً ان کی پہلی کتاب نثر میں چھپی ’’علم الاقتصاد‘‘ 1904ء میں۔ شاعری میں سب سے پہلی کتاب ’’اسرارِ خودی‘‘ پھر ’’رموزِ بے خودی‘‘ پھر ’’پیامِ مشرق‘‘ اُس کے بعد’’بانگِ درا‘‘ چھپی ہے۔ ان سب اورباقی کتب کی بھی اشاعت کی کیا تاریخ وترتیب ہے؟ یہ بھی تھا کہ ایک کتاب ایک بار چھپنے کے بعد جب دوسری مرتبہ چھپتی تھی تو علامہ اقبال اس میں ترمیم کرتے تھے۔ وہ ترامیم کیا تھیں تحقیقی اعتبار سے ان کی نشاندہی اوران کاکھوج لگاناضروری تھا کیونکہ اس سے شاعر کی ذہنی تبدیلی کا پتا چلتا ہے۔ اقبال نے بعدکے ایڈیشنوں سے بعض اشعار نکال دیے اور ان کی جگہ نئے شعر شامل کر یے مثلاً اسرارِ خودی، میں حافظ شیرازی کے بارے میں بڑے سخت شعر تھے لوگوں نے بڑے اعتراض کیے۔ اکبر الٰٰہ آبادی اور خواجہ حسن نظامی بھی ناراض ہوئے تو دوسرے ایڈیشن میں انھوں نے ان اشعار کو نکال دیا۔ جب تیسرا ایڈیشن آیا تو اقبال نے پھر ترامیم کیں تو میں نے اپنے مقالے میں وضاحت کے ساتھ ان سب ترامیم اورتبدیلیوں کی وضاحت کی جومختلف شعری مجموعوںمیںعلامہ اقبال نے کیں۔ مثلاً ’’بانگ درا‘‘ کا تیسرا ایڈیشن حتمی نسخہ ہے۔ اسی طرح’’ پیامِ مشرق‘‘ کا دوسرا ایڈیشن اس کا حتمی نسخہ ہے۔ اس لیے اقبال کی فکر کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کی ذہنی تبدیلیوں کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری تھا۔ اوریہ کام بہت پھیلا ہوا تھا کیونکہ ان کی چار کتابیں اردو کی ہیں سات فارسی کی ہیںپھر نثر کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ کے انگریزی خطبات ہیں جنھیں خطبات مدراس بھی کہتے ہیں اس کے دوسرے ایڈیشن میں بھی تبدیلیاں کی گئیں، میںنے ان کی بھی نشاندہی کی۔ یہ سارا کام اس لحاظ سے تحقیقی اہمیت کا حامل ہے کہ اب جو لوگ اقبال پر تحقیق کرتے ہیں انھیں اس مقالے سے رہنمائی ملتی ہے ۔ س: ڈاکٹر صاحب! علامہ اقبال اپنے نظریات اور تخلیقی عمل میں کن شخصیات سے متاثر تھے جبکہ ان کا زمانہ برصغیر میں مسلمانوں کے زوال اور آشوب کا تھا؟ج: علامہ اقبال کی فکر اوران کے نظریات دراصل ان کی شخصیت کاعکس ہیں،اوراقبال کی شخصیت کی تشکیل میں تین افراد کا بنیادی عمل دخل ہے۔ ایک تو خود ان کے والد تھے جو بڑے دُرویش منش اور صوفی بزرگ تھے۔ انھوں نے لڑکپن ہی سے اقبال کی تربیت ایک خاص نہج پر کی ،مثلابیٹے کویہ نصیحت کی کہ قرآن پاک کو ایسے پڑھاکرو جیسے یہ تم پرنازل ہورہاہے۔یاجیسے یہ تمھارے جسم و جاں کا حصہ بن رہا ہے۔دوسری شخصیت مولوی سید میر حسن کی ہے۔ان کا بھی اقبال پر بڑا گہرا اثر ہے۔ وہ ان کے استاد تھے اوراقبال کے اندرعلمی وادبی ذوق پروان چڑھانے میں ان کابڑادخل ہے۔تیسرے شخص پروفیسرآرنلڈتھے، جو فلسفے کے استاد تھے۔ ان کا اقبال پراتنا اثر تھا کہ ا قبال نے پروفیسر آرنلڈ کے لیے نظم لکھی ’نالۂ فراق‘ جو بانگِ درا میں شامل ہے۔ وہ جب یہاں سے ریٹائر ہو کر جا رہے تھے تواقبال نے یہ نظم لکھی تھی’’تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سودائے علم‘‘ اور یہ پوری نظم اقبال پرآرنلڈ کے احسانات اور فیوض کااعتراف ہے۔ اس نظم کاایک اورمصرع ہے ’’توڑ کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو‘‘۔ 1904ء میں یہ نظم کہی اور 1905ء میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اقبال آرنلڈ کے پیچھے پیچھے انگلستان پہنچ گئے اور تین سال میں کیمبرج‘ لنکنز ان اور میونخ سے تین ڈگریاں حاصل کیں۔ تویہ تین ہستیاں ہیںجنھوں نے اقبال کی شخصیت کی تشکیل کی۔ ویسے میں سمجھتاہوں کہ اقبال کو صاحب اقبال اور باکمال بنانے میں ان کی والدہ اورسکاچ مشن کالج اورکیمبرج کے ان کے اساتذہ کابھی خاصا دخل ہے۔س: ڈاکٹر صاحب! علامہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے کیا خدوخال تھے اور وہ اس کے لیے کیسا نظام پسند کرتے تھے؟ج:اقبال نے جس ریاست کی بات کی ہے،اس کابنیادی نکتہ یہ ہے کہ حاکمیت یاساورنٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے،یعنی ’’سروری زیبا فقط اس ذاتِ بے ہمتاکوہے‘‘۔اقبال مغربی جمہوریت کے خلاف تھے کیونکہ اس میں حاکمیت عوام کی ہوتی ہے مگر اقبال عوام کو نہیں اللہ تعالیٰ کو حاکم مانتے ہیں۔کہتے ہیں’’حکمراں ہے اک وہی ،باقی بتانِ آزری‘‘۔معاف کیجیے اقبال کی نظر میں تو ہم آج کل بتانِ آزری کو پوج رہے ہیںاور اسی لیے خوار ہورہے ہیں۔…رہی یہ بات کہ اقبال کیسانظام پسند کرتے تھے ؟ قائداعظمؒ سے ان کی خط کتابت دیکھیے ،جس میں انھوں نے کہا کہ ہمارے مسائل کا حل نہرو کی لادینی سوشلزم میں نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامیہ کے نفاذ میں ہے۔ لہٰذا یہ بالکل واضح ہے کہ وہ مسلمانوں کی نئی ریاست کے لیے سیکولر یا سوشلسٹ نظام تجویز نہیں کرتے تھے۔ وہ دین اور سیاست کو بھی الگ الگ نہیں سمجھتے تھے۔ س: علامہ اقبال کے نزدیک اجتہاد کی کیا اہمیت ہے؟ج: دیکھیے علامہ اقبال زندگی میں جس انقلاب پر زور دیتے ہیں،مثلاً کہتے ہیں: عجس میں نہ ہو انقلاب ، موت ہے وہ زندگیتوان کے مجوزہ انقلاب میں اجتہادناگزیر ہے اور ایک بنیادی نکتہ ہے۔دورحاضرمیں کسی قوم کو،خاص طورپرمسلم امہ اپنی بقا اورترقی کے لیے اجتہاد کی اشدضرورت ہے،اس لیے اقبال نے نئے زمانے میں نئے صبح وشام پیداکرنے کی تلقین کی ہے۔ان کے نزدیک طرز کہن پراڑنا،جموداور موت کی علامت ہے۔مگر یہ نہ ہو کہ اجتہاداورآئین نو کے شوق میں اپنی تہذیب کی بنیادوں ہی سے منحرف ہو جائیں۔اقبال کے نزدیک ہر ایراغیرا اجتہاد کااہل نہیں۔س: ڈاکٹر صاحب! علامہ اقبال وسیع المطالعہ تھے‘ انھوں نے اردو فارسی میں شاعری بھی کی اور نثر بھی لکھی۔ برصغیر کی سیاست میں بھی ان کا بھرپور کردار رہا۔ وہ ایک فلاسفر بھی تھے۔ا نہوں نے کالج میں اردو‘ فارسی فلسفہ اور انگریزی بھی پڑھائی ان سب صفات کے ہم آہنگ ہونے سے اقبالؒ کی کیا شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ ج: دیکھیے علامہ اقبال کثیر المطالعہ اور جامع الحیثیات شخص تھے۔ وہ استاد بھی تھے‘ شاعر بھی تھے اور سیاست دان بھی مگر ان کی دیگر صفات ان کی شاعری کے تابع ہیں کیونکہ وہ بنیادی طور پر شاعر تھے۔ انھوں نے ہر شعبے میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں اور کچھ ہدایات دی ہیں۔ ان کی شاعری پر غور کرنے اورتامل کرنے سے نئے سے نئے نکات سامنے آتے ہیں۔ دنیا کی چالیس زبانوں میں ان کی تخلیقات کے تراجم ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے کلام میں ایک کشش ،جامعیت اورہمہ گیری پائی جاتی ہے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو 15 اگست کی رات کوبھارت کی اسمبلی کاافتتاح اقبال کے’’ ترانہ ہندی‘‘ سے ہوا۔کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کی شخصیت کی دل نوازی ایک حدتک ان کے کٹر مخالفین کے لیے بھی قابل قبول تھی۔س: ڈاکٹر صاحب! علامہ اقبال نے جہاں حافظ اور مولانا روم کو پڑھا، وہاں مارکس، لینن، گوئٹے اور نٹشے کا بھی مطالعہ کیا اور انھوں نے ان کو اپنی شاعری میں بھی جگہ دی مگر ہر نظام کو اسلام کی کسوٹی پر پرکھا اور اسلام کو ہی بہترین نظام قرار دیا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ج:کہنا چاہیے کہ جن شخصیات کو انھوں نے پڑھا ان کا ذکر ان کی شاعری میں آیا ہے۔ اقبال نے سب کو پڑھا اور سب سے استفادہ کیا لیکن اقبال کی فکر کا جو سب سے بڑا ماخذ ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اور ان کے نزدیک جو سب سے عظیم شخصیت ہے وہ نبی کریمؐ کی ہے جن سے وہ سب سے زیادہ متاثر تھے۔ اس کے بعد مولانا رومی ہیں‘ اس کے بعد دوسرے لوگ بلاشبہ انھوں نے دوسرے لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ اثر قبول کیااوربعضچیزوںکو انھوں نے سراہا گویا جہاں سے بھی انھیں حکمت ودانش کی کوئی چیز ملی، اسے اپنی فکر کا حصہ بنا لیا۔ س: ڈاکٹر صاحب اقبال کے وسیع مطالعے اور فارسی و عربی زبانوں پر عبور ہونے کے سبب ان کا کلام مفرس اور معرب ہے اور اس میں مشکل پسندی پائی جاتی ہے۔ کیا یہ ابلاغ عامہ کے راستے میں حائل تو نہیں؟ج: ایک تو یہ ہے کہ اقبال کے زمانے میں فارسی زبان کی روایت بہت پختہ تھی۔ فارسی پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی ۔دوسری بات یہ کہ ایک بار کچھ دوستوں نے اقبال سے شکوہ کیاکہ آپ فارسی میں سب کچھ کہتے ہیں ،اردو والے منتظر رہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا جواب تھا It comes to me in Persian. باقی مشکل کی بات تو یہ ہے کہ اب ہمارامعیار تعلیمبہت نیچے آ گیاہے اورہمیں اقبال کااردو کلام بھی فارسی کی طرح لگتا ہے۔ س: ڈاکٹر صاحب! اقبال کے حوالے سے دنیا کے متعدد ممالک میں کانفرنسیں ہوتی رہیںاور پاکستان میں بھی اقبالیات کے موضوع پر سیمینار ہوتے رہے ہیں آپ کی ان سیمینارز اور کانفرنسوں میں اندرون ملک اور بیرون ملک بھرپور شرکت رہی، کچھ ان کا احوال بیان کیجیے۔ ج: اقبال کے حوالے سے کانفرنسوں کا آغاز اقبال کے زمانے ہی میں ہوگیا تھا۔ یہ روایت پاکستان بننے کے بعد پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ اور کانفرنسوں کا یہ سلسلہ دنیا کے پیشتر ممالک تک پھیلا ہوا ہے مجھے بھی ایسی دس بارہ کانفرنسوں میں شرکت کاموقع ملا۔ دوتین مرتبہ پاکستان میں‘ دو دفعہ بھارت میں‘ ایک دفعہ ترکی میں‘ ایک مرتبہ بلجیم میں‘ ایک ایک دفعہ برطانیہ اوراسپینمیں جانے کا موقع ملا۔ جو کانفرنس دسمبر 1977ء میں لاہور میں ہوئی جب علامہ اقبال کا سو سالہ جشن منایا گیا ،وہ سب سے بڑی کانفرنس تھی۔اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جنرل ضیاء الحق اجلاس کے صدرتھے۔ بشیرحسین ناظم نے کلام اقبال پڑھا اور سماںباندھ دیا۔ جنرل خوش ہوگئے۔ فرمائش کی کہ ایک اورغزل پڑھیں ،بشیرصاحب نے اتفاقاًیا شاید شرارتاًبال جبریل کی وہ غزل شروع کی ’’دل بیدار فاروقی…‘‘ ناظم صاحب غزل پڑھ رہے تھے اورجنرل صاحب سن سن کر جھوم رہے تھے،جب آخری شعرپرپہنچے اور وہ یہ تھا:خدا وندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیںکہ دُرویشی بھی عیاری ہے ، سلطانی بھی عیاریتو یہ شعر پڑھتے ہوئے بشیرحسین ناظم نے معنی خیزطورپر ضیاء الحق کی طرف دیکھا۔٭٭٭