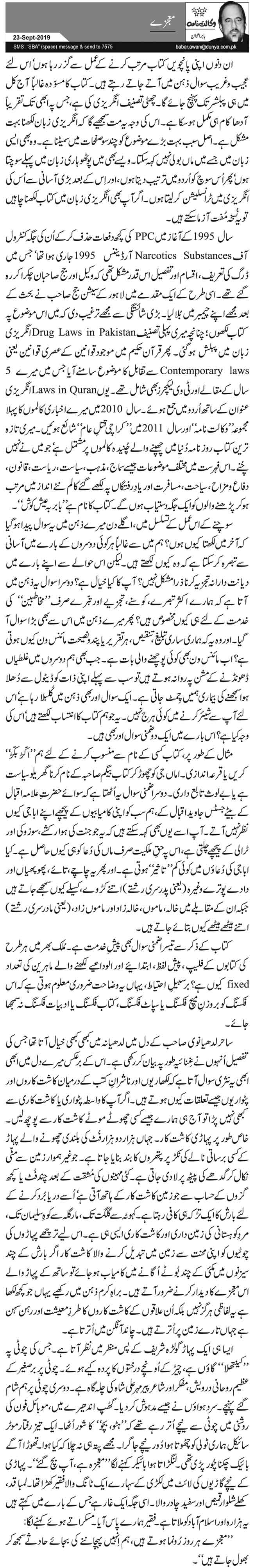تاریخ اشاعت 2019-09-23
معجزے
ان دنوں اپنی پانچویں کتاب مرتب کرنے کے عمل سے گزر رہا ہوں‘ اس لئے عجیب و غریب سوال ذہن میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ کتاب کا مسوّدہ غالباً آج کل میں ہی پبلشر تک پہنچ جائے گا۔ چھٹی تصنیف انگریزی کی ہے، جس پہ ابھی تک تقریباً آدھا کام ہی مکمل ہو سکا ہے۔ اس کی وجہ یہ مت سمجھیے گا کہ انگریزی زبان لکھنا بہت مشکل ہے۔ اصل سبب بہت بڑے موضوع کو چند سو صفحات میں سمیٹنا ہے۔ وہ بھی ایسی زبان میں جسے میں ماں بولی نہیں کہہ سکتا۔ ویسے بھی میں پوٹھوہاری زبان میں پہلے سوچتا ہوں‘ پھر اُس سوچ کو اُردو میں ترتیب دیتا ہوں، اور اِس کے بعد بڑی آسانی سے اُس کی انگریزی میں ٹرانسلیشن کر لیتا ہوں۔ اگر آپ بھی انگریزی زبان میں کتاب لکھنا چاہیں تو یہ نُسخہ مُفت آزما سکتے ہیں۔
سال 1995 کے آغاز میں PPC کی کچھ دفعات حذف کر کے اُن کی جگہ کنٹرول آف Narcotics Substances آرڈیننس 1995 جاری ہوا تھا‘ جس میں ڈرگ کی تعریف ، اقسام اور تفصیل اس قدر مشکل تھی کہ وکیل اور جج صاحبان چکرا کر رہ گئے تھے۔ اسی طرح کے ایک مقدمے میں لاہور کے سیشن جج صاحب نے بحث کے بعد مجھے اپنے چیمبر میں بُلا لیا۔ بڑی شائستگی سے مجھے ترغیب دی کہ میں اس موضوع پہ کتاب لکھوں؛ چنانچہ میری پہلی تصنیف Drug Laws in Pakistan انگریزی زبان میں پبلش ہو گئی۔ پھر قرآن حکیم میں موجود قوانین کے عصری قوانین یعنی Contemporary laws سے تقابل کا موضوع سامنے آیا جس میں میرے 5 سال کے مقالے اور ٹی وی لیکچرز بھی شامل تھے۔ یوں Laws in Quran انگریزی عنوان کے ساتھ اُردو میں جمع ہوئے۔ سال 2010 میں میرے اخباری کالموں کا پہلا مجموعہ ''وکالت نامہ‘‘ اور سال 2011 میں ''کراچی قتلِ عام‘‘ شائع ہوئیں۔ میری تازہ ترین کتاب روز نامہ دُنیا میں چھپنے والے چُنیدہ کالموں پر مشتمل ہے‘ جو میں نے نہیں چُنے۔ اس فہرست میں مختلف موضوعات جیسے سماج، مذہب، سیاست، ریاست، قانون، دفاع و مزاح، سیاحت، مسافرت اور یادِ رفتگاں پہ لکھے گئے کالم نئے انداز میں مرتب ہو کر پڑھنے والوں کو ایک جگہ دستیاب ہوں گے۔ کتاب کا نام ہے '' بابر بہ عیش کوش‘‘۔
سوچنے کے اس عمل کے تسلسل میں، اگلے دن میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ آخر میں لکھتا کیوں ہوں؟ ہم میں سے غالباً ہر کوئی دوسروں کے بارے میں آسانی سے تبصرہ کر سکتا ہے کہ وہ کیوں لکھتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے اپنے بارے میں دیانت دارانہ تجزیہ کرنا ذرا مشکل نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے اکثر تبصرے، کوسنے، تجزیے اور تبّرے صرف ''مخاطبین‘‘ کی خدمت کے لئے ہی کیوں مخصوص ہیں؟ پھر میرے ذہن میں اس سے بھی بڑا سوال آ گیا۔ اور وہ یہ کہ ہماری ساری تبلیغ، تنقیص، ہر تقریر یا پند و نصیحت مائنس ون کیوں ہوتی ہے؟ اب مائنس ون بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ جب بھی ہم دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈنے کے مشن پہ روانہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ذات کو ڈیٹول سے دُھلا ہوا سمجھنے کی بیماری ہمیں چِمٹ جاتی ہے۔ ایک سوال اور بھی ذہن میں کُلبلا رہا ہے‘ اس لئے آپ سے شیئر کرنے میں کوئی ہرج نہیں۔ یہ جو ہم کتاب کا انتساب لکھتے ہیں‘ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بارے میں ایک دو ضمنی سوال اور بھی ہیں۔
مثال کے طور پر، کتاب کسی کے نام سے منسوب کرنے کے لئے ہم ''اکّڑ بکّڑ‘‘ کریں یا قرعہ اندازی۔ اماں جی کو چھوڑ کر کتاب بیگم صاحبہ کے نام کرنا گھریلو سیاست ہے یا بے لوث تابع داری۔ دوسرا ضمنی سوال یہ اُٹھتا ہے کہ سوائے حضرتِ علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال کے، ہم سب کو اپنی کامیابیوں کے پیچھے اپنے ابا جی کیوں نظر نہیں آتے۔ آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جنت کی ہوا رکشے، سوزوکی اور ٹرالی کے پیچھے چلتی ہے، اس پہ حقِ ملکیت صرف ماں کی دُعا کو ہی کیوں حاصل ہے۔ کیا ابا جی کی دُعائوں میں کوئی کم ''تاثیر‘‘ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ چاچے، تائے، پھوپھیاں اور دادے پوترے وغیرہ (یعنی پدر سری رشتے) اتنے کڑوے، کسیلے کیوں سمجھے جاتے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں خالہ، ماموں، خالہ زاد اور ماموں زاد، (یعنی مادر سری رشتے) اتنے میٹھے میٹھے کیوں بتائے جاتے ہیں۔
کتاب کے ذکر سے تیسرا ضمنی سوال بھی پیشِ خدمت ہے۔ مُلک بھر میں ہر طرح کی کتابوں کے فلیپ، پیش لفظ، ابتدائیے اور الوداعیے لکھنے والے ماہرین کی تعداد fixed کیوں ہے؟ بر سبیلِ احتیاط، یہاں یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اس فکسنگ کو بر وزنِ میچ فکسنگ یا سپاٹ فکسنگ، کتاب فکسنگ یا ادبیات فکسنگ نہ سمجھا جائے۔
ساحر لدھیانوی صاحب کے دل میں لدھیانہ میں کبھی کبھی خیال آتا تھا جس کی تفصیل اُنہوں نے غِنائیہ طور پہ بیان کر رکھی ہے۔ اس کے بر عکس میرے دل میں ابھی ابھی یہ نثری سوال آتا ہے کہ لکھاریوں اور ناشرانِ کتب کے درمیان کاشت کاروں اور پٹواریوں جیسے تعلقات کیوں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا واسطہ پٹواری یا کاشت کاری سے کبھی نہیں پڑا تو آج ہی ہمارے جیسے کسی چھوٹے موٹے کاشت کار سے پوچھ لیں۔ خاص طور پر پہاڑی کاشت کار۔ جہاں ہزار دو ہزار فُٹ کی بلندی چھونے والے پہاڑ کے کسی برساتی نالے کی نکڑ پر پتھروں کا بند بنایا جاتا ہے۔ جو غیر ہموار زمین سے مٹّی نکال کر گدھے کی پیٹھ پر لادی جاتی ہے۔ کئی مہینوں کی مُشقت کے بعد چند فُٹ یا کچھ گزوں کے حساب سے جو زمین کاشت کار کے ہاتھ آتی ہے‘ اُسے دریا بُرد کرنے کے لئے بارش کا ایک تڑکہ ہی کافی رہتا ہے۔ کہوٹہ سے گلگت تک، مارگلہ سے کوہِ سلیمان تک، مردِ کوہستانی کی زمین داری اور کاشت کاری ایسی ہی ہے۔ اس لیے ترچھے پہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنی محنت سے زمین میں تبدیل کرنے والا کاشت کار اگر بارش کے چند سیزنوں میں مکئی کے چند بُوٹے اُگانے میں کامیاب ہو جائے تو ساتھ کے پہاڑ والے اس معجزے کا دیدار کرنے ضرور آتے ہیں۔ براہِ کرم ذہن میں رکھیے یہاں جو کچھ لکھا ہے یہ لفاظی ہرگز نہیں بلکہ اُن علاقوں کے کاشت کاروں کا طرزِ معیشت اور رہن سہن ہے جہاں تارے زمین پر اُترتے ہیں۔ چاند آنگن میں اُترتا ہے۔
ایسا ہی ایک پہاڑ گولڑہ شریف کے پس منظر میں نظر آتا ہے۔ جس کی چوٹی پہ ''کینتھلا‘‘ گائوں ہے، چیڑ کے اُونچے درختوں کا پردہ کیے ہوئے۔ چوٹی پر بر صغیر کے عظیم روحانی درویش، مفکر اور شاعر پیر مہر علی شاہ کی چلہ گاہ ہے۔ دوسری چوٹی پر ہم شام گئے پہنچے۔ سرد ہوائوں نے جیسے مدہوش کر دیا۔ گھُپ اندھیرے میں، موبائل فون کی روشنی میں چوٹی سے نیچے اُتر رہے تھے کہ ''ہٹو، بچو‘‘ کا شور اُٹھا۔ ایک تیز رفتار موٹر سائیکل ہماری ٹولی کو چھُوتا ہوا دُور نیچے جا گرا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ہوا۔ تھوڑا آگے بائیک چکنا چُور پڑی تھی۔ لنگڑاتا ہوا بائیکر کہنے لگا ''معجزہ ہے ، آپ بچ گئے‘‘۔ پہاڑی کے نیچے گاڑیوں کی لائٹ میں لکڑی کے سہارے ایک ٹانگ والا فقیر کھڑا تھا۔ لمبا قد، کھلے شلوار قمیص اور سفید چادر والا۔ اسی جگہ ایک غار ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہزارہ اور اسلام آباد کو ملاتا ہے۔ فقیر ہمارے پاس آیا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا :
''معجزے ہر روز رُونما ہوتے ہیں، ہم اِنہیں پہچاننے کی بجائے حادثے سمجھ کر بھول جاتے ہیں‘‘۔
بابر اعوان کے مزید کالمز
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں 2026-02-27 کوئی اسے علاج کیوں مانے؟ 2026-02-20 بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران 2026-02-16 Too Little Too Late 2026-02-13 سیف سِٹی سائنس 2026-02-09 احتجاج کیوں نہ ہو؟ 2026-02-06 عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟ 2026-01-30 فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟ 2026-01-26 افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی 2026-01-23 صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں 2026-01-19