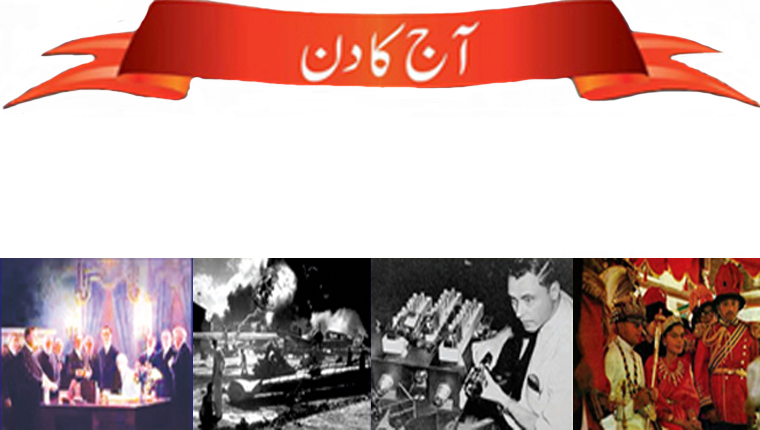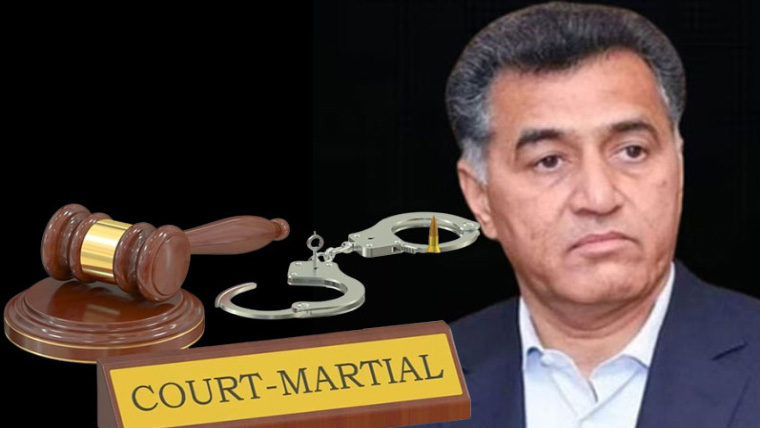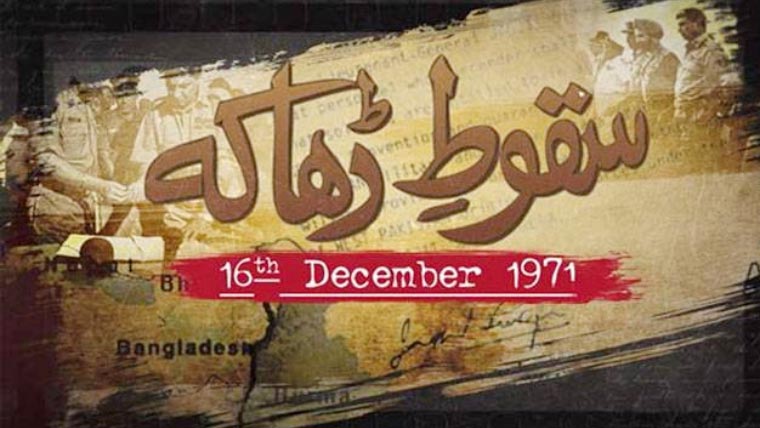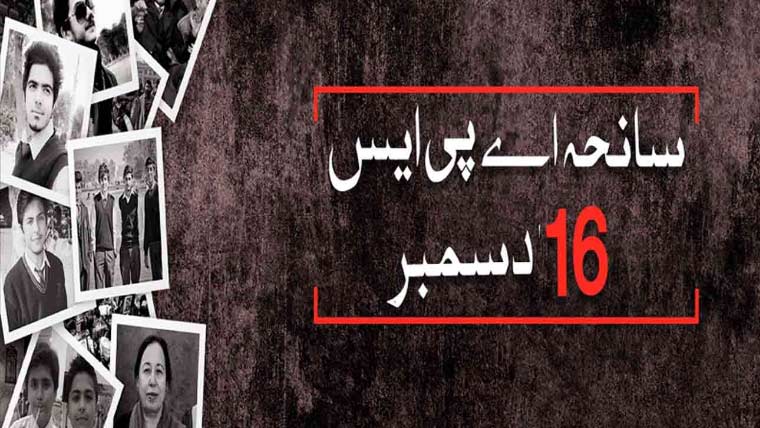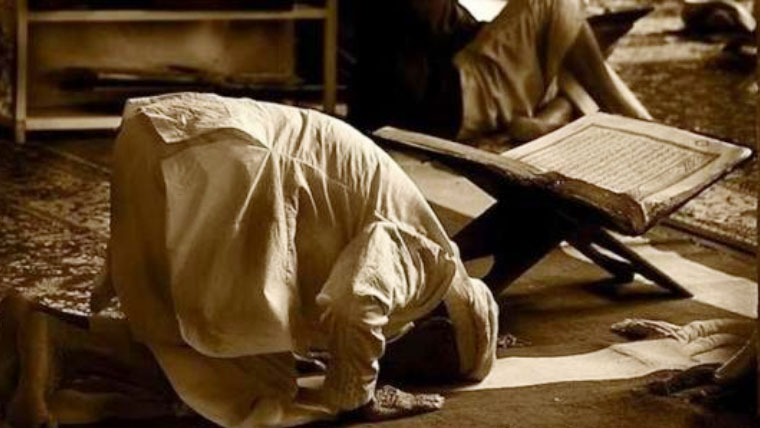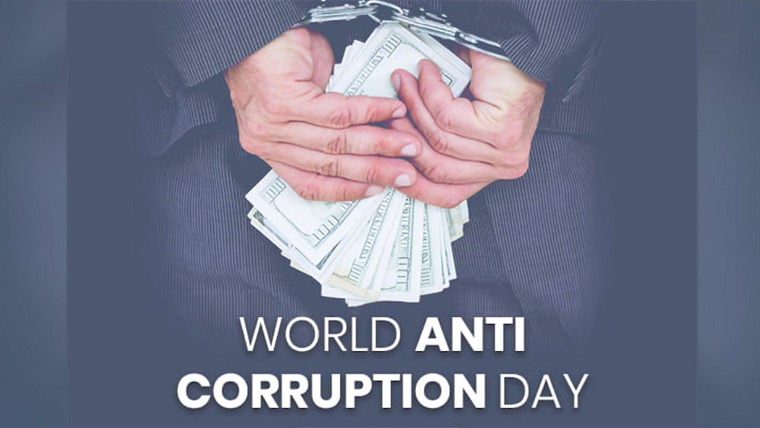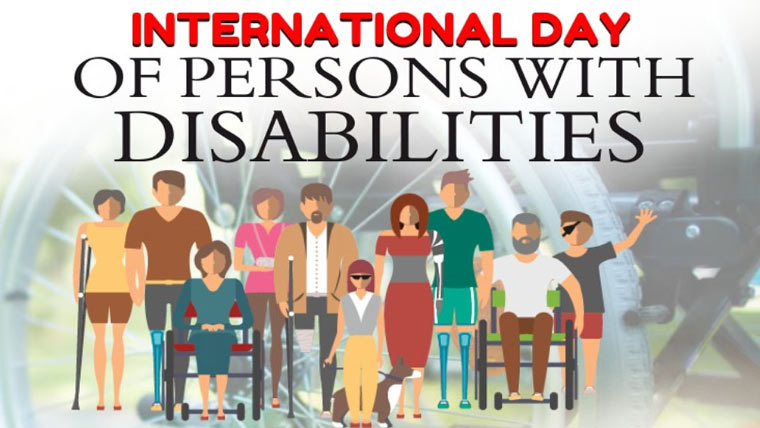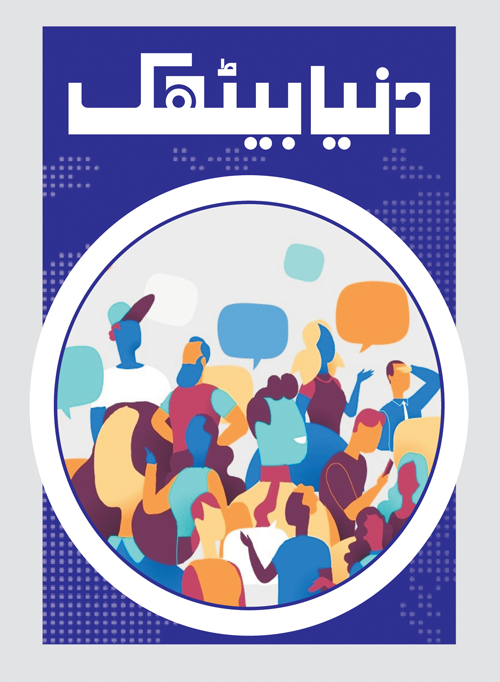پہلی عالمی جنگ کی اصل وجہ معاشی بالادستی!

اسپیشل فیچر
1776ء میں چھپنے والی ایڈم سمتھ کی کتاب ''ویلتھ آف نیشنز‘‘ (The Wealth of Nations)نے اقوام یورپ میں ایک نئی سوچ کو جنم دیا تھا جس کے بعد قوموں کی معاشی ترقی کیلئے باقاعدہ تحقیق کی جانے لگی اور اقوام یورپ معاشی وسائل اور ذرائع کے حصول کیلئے ایک نئے طریقہ سے مصروف عمل ہو گئیں۔ ''بارٹر سسٹم‘‘ کی جگہ بین الاقوامی تجارت و معیشت نے لے لی تھی۔قومیں اپنی تمام ضرورتیں اپنے ہی وسائل سے پوری کرنے کی بجائے ایک یا چند ایک پیداواری صلاحیتوں میں تخصیص کی خواہاں نظر آتی تھیں اور دیگر ضروریات کیلئے عالمی منڈی کی طرف رجوع کرنے لگی تھیں۔ برطانوی استعمار کے پھیلائو کی وجہ بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ پہلے پہل تو وہ تجارت کے عمومی مقاصد کیلئے یورپ سے باہر نکلے اور ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ تک جا پہنچے اور وہاں کے سادہ لوح عوام کو اپنا محکوم بنا لیا۔
یورپ کی تمام اقوام تجارت و معاشی ترقی اور خوشحالی کیلئے یورپ کی تنگ سرزمین سے نکل کھڑی ہوئی تھیں اور اس طرح عالمی کھوج اور عالمی پیداواری ذرائع کی تحقیق اور ان سے استفادہ کی سرتوڑ کوششیں جاری تھیں۔ ہر ملک اپنی بیرون یورپ تجارت کیلئے بحریہ کی تشکیل کیلئے کوشاں تھا۔جس ملک کیلئے یہ آسانی سے ممکن نہ تھا تو وہ دیگر ممالک کے بحری جہازوں کے ذریعے اپنے تجارتی کاروان اور قافلے روانہ کر رہا تھا۔ بین الاقوامی تجارت کا رجحان نیا نیا قائم ہوا تھا، جس کے تحت ممالک دنیا بھر کے دور دراز علاقوں کی پیداوار سے اپنے ملک کی ضرورت کے مطابق اجناس خورو نوش اور دیگر اشیاء ضرورت خرید کرتے اور بدلے میں اپنے ممالک کی تیار کردہ اجناس و اشیاء انہیں فروخت کرتے یا ان سے خریدے ہوئے مال کی قیمت ادا کرتے۔
یورپ کی باہمی جنگوں سے یورپی ماہرین و دانشوروں کو اس بات کا مکمل طور پر احساس ہو چکا تھا کہ جنگ لڑنے کیلئے کسی ملک کی مضبوط معیشت اور مستحکم سفارتی تعلقات انتہائی ضروری ہیں۔ اپنے ارد گرد منڈلانے والے خطرات کے پیش نظر ہر ملک معاشی و اقتصادی طور پر دیگر ہمسایہ ممالک سے سبقت لے جانے کا خواہاں نظر آتا تھا۔ یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ معاشی طور پر مستحکم ملک اپنے مد مقابل معاشی طور پر غیر مستحکم یا کم مستحکم ملک پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس طرح معاشی سبقت و استحکام دوسروں کے کمزور اور اپنے ملک کے مضبوط ہونے کی علامت تھی۔بیسویں صدی کے آغاز پر اقوام یورپ معاشی کامیابی کی خواہش میں ایک دوسرے سے مخاصمت کے جذبے سے سرشار تھیں۔ نہر سویز اس لئے انتہائی اہم مسئلہ بن چکی تھی کہ ایشیائی بالادستی قائم کرکے دیگر ممالک کے گزرنے والے بحری جہازوں سے محصول حاصل کیا جاسکتا تھا۔
برطانوی شاہی بحریہ اپنی بلند شان و شوکت اور وسعت کے باعث عالمی تجارت کے تمام بہترین راستوں پر قابض و حاکم تھی۔ دیگر ممالک اس بالادستی سے سخت نالاں تھے، کیونکہ اس طرح اپنی تجارت سے ہونے والی آمدن کا کچھ حصہ برطانیہ کو پیش کرنے کے پابند تھے۔ جو برطانوی معیشت کیلئے بہتر اور ان ممالک کی معیشت کیلئے سخت نقصان دہ تھا۔ فولاد سازی، صنعت سازی، کیمیائی مصنوعات کی تیاری، برقی و معدنی ذرائع سے توانائی کا حصول اور زرعی ترقی کیلئے ہر ملک اپنی اپنی سطح پر کوششوں میں مصروف تھا۔ ان مفادات کے حصول کیلئے یورپی ممالک اپنی تجارت کا دائرہ کار بڑھانے اور ایسے ممالک جہاں سے ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، پر انحصار کرنے پر مجبور تھے۔ اس طرح ملکی مفادات کے حصول کیلئے ایک دوسرے پر بھی انحصار کیا جاتا تھا۔ زیادہ طاقتور ممالک اس انحصار سے ناجائز فوائد بھی حاصل کرتے اور مفادات کے حصول میں پیدا ہونے والی رکاوٹیں باہمی رنجش و تعصب کے جذبات کی آبیاری کا ذریعہ بن کر یورپی ممالک کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرنے کی وجہ بنیں۔
جرمنی عالمی تجارت میں سبقت لے جانے کی خواہش میں جدید ترین بحری بیڑے کے قیام میں مصروف عمل تھا۔ دوسری طرف جرمنی کے بحری بیڑے کے طاقتور ہونے سے برطانوی سمندری اجارہ داری کو شدید خطرہ تھا۔ اور اسی تشویش اور تعصب نے برطانیہ کو جرمنی کے خلاف میدان کار زار سجانے اور فرانس اور روس کے ساتھ مفادات کے ٹکرائو کے باوجود ہم صف ہونے پر آمادہ کیا۔ یہاں یہ مطلب ہرگز نہیں کہ برطانیہ ، فرانس اور روس ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے بلکہ اپنے ارد گرد ایک ابھرتی ہوئی معاشی و اقتصادی قوت کو دیکھ کر یہ ممالک سخت پریشان ہو گئے تھے اور کچھ دیر کیلئے اپنی باہمی مخالفتوں کو بھول کر متحد ہو چکے تھے۔
فرانس بیرونی سرمائے کی فراوانی کے باعث دیگر ممالک کو سودی قرضوں کی فراہمی پر اپنی معیشت کو استوار کر رہا تھا۔ روس صنعتی ترقی اور فولاد سازی کیلئے کوشاں نظر آتا تھا۔ جرمنی فولاد سازی، کیمیائی مصنوعات کی تیاری، بھاری مشینری کی تیاری اور برقی پیداوار میں اضافے کے اسباب پر غور کر رہا تھا۔ برطانیہ عالمی سوداگر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ یہ سب اقدامات معاشی و اقتصادی استحکام و ترقی کیلئے روبہ عمل لائے جا رہے تھے اور ان اقدامات کے ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے پر کڑی نظر بھی رکھی جا رہی تھی تاکہ کسی مقابل کے زیادہ طاقتور ہو جانے کی صورت میں حصول طاقت کے جملہ ذرائع سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے۔
یورپی ممالک کے مابین ہونے والی جنگیں گزشتہ صدی کے پہلے نصف کی جنگوں کی طرح صرف عددی و علاقائی برتری کیلئے نہیں لڑی جاتی تھیں بلکہ یہ جنگیں عالمی منڈیوں، پیداواری علاقوں اور توسیعی مقاصد کے حصول کیلئے لڑی جا رہی تھیں اور ان سب مقاصد کے حصول سے ایک ہی بنیادی مقصد حاصل ہو سکتا تھا اور وہ تھا معاشی بالادستی!۔